ایک شام
قرۃالعین حیدر
اوفّوہ بھئی…اللہ ۔ ممی اچھے تو ہیں ہم بالکل۔ ذرا یوں ہی ساسر میں درد ہوجانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اب ہمیں دودھ اوولٹین پینا پڑے گا۔
اور ممی گھبرائی ہوئی کمرے سے چلی گئیں۔ شاید ڈاکٹر کو فون کرنے۔ میں نے لیمپ کا رخ مسہری کی طرف کرکے آسکر وائلڈ کی ایک کتاب اٹھالی۔ ڈرائنگ روم میں سے ریڈیو کی آواز آرہی تھی۔ وہی اختری فیض آبادی کی سمع خراش تانیں___ اور پھر مجھے یاد آیا کہ ابھی کالج کا بہت سا کام کرنا باقی ہے اور اگلے ہفتے سے ششماہی امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ دودھ اوولٹین اورسوڈا بائی کار۔ میں نے جھنجھلا کر کتاب نیچے قالین پر پھینک دی اور لیمپ کے نیلے شیڈ پر بنے ہوئے چینی نقش ونگار کو غور سے دیکھنے لگی۔ اور پھر خیالات کہاں کہاں بھٹک گئے۔ لیمپ کے سرخ شیڈ اور آدھے جلے ہوئے سگریٹ___ بوہیمیا___ لیٹن کو اٹر___ تصویروں کے آڑے ترچھے بے تکے سے نقوش۔ ترچھی اور بڑی بڑی آنکھیں اور بے حد پتلی اور لمبی انگلیاں ___ پس منظر میں دھندلا دھندلا نہ معلوم کیا۔ اور دھواں سا بل کھاتا اور اوپر کو اٹھتا ہوا۔ لمبے لمبے فرانسیسی دریچے اور ان میں حجابؔ کے افسانے۔ نپولین اور لارڈ نیلسن۔ بے چارے کی ایک آنکھ ضائع ہوگئی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی تو درد ہورہا ہے___ اور ایک لیڈی ہملٹن تھی___ اور پھر یہ اتنے سارے ’’ازم___‘‘ ’’سوشلزم‘___‘ ’’کمیونزم‘‘ ’’فاشزم___‘‘ ’’ناتسی ازم___‘‘۔ رزم وبزم___ اوفوہ بھئی___ توبہ۔
اور میری نظر رسالہ ’’ادب لطیف‘‘ کے تازے پرچہ پر پڑگئی جو پاس کی میز پر رکھا ہوا تھا___ واقعی یہ نیا ادب بھی کیا کمال کی چیز نکلی ہے___ ترقی پسند ادب___ حسین پگڈنڈیاں۔ خوب صورت ہوائیں۔ جنتا۔ سماج___ مزدور___ روٹی___ بھوک بھوک بھوک ۔
سچ مچ مجھے بھوک معلوم ہورہی تھی ۔ کیونکہ میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ اتنے میں ممی دودھ اوولٹین لے آئیں۔
اور سونے سے پہلے ممیؔ نے مجھ سے کہا کہ میں کل شام کو کہیں اور نہ جائوں۔ کیونکہ پرویزؔ رومانی ’’کافی ہائوس ‘‘ میں خالو جان کی رخصتی پارٹی دے رہے ہیں۔
خالو جان بے چارے جو ہماری سرکار والاتبارکی فوج میں لفٹننٹ کرنل ہیں۔ تبدیل ہوکر پونا جارہے تھے۔ اور ان کی رخصتی دعوتوں کا سلسلہ کئی ہفتے پہلے سے شروع ہوچکا تھا۔ یہ پرویزؔ رومانی صاحب جو تھے یہ ترقی پسند شاعری کرتے تھے اور محکمہ سپلائی میں ملازم ہونے سے قبل سبھاش بوس کے چیلے بھی رہ چکے تھے۔
اور دوسرے دن سہ پہر کے بعد ’’ کافی ہائوس‘‘ میں فوجی افسروں کے علاوہ پرویزؔ صاحب کے ’’کامریڈز‘‘ یعنی ترقی پسند مصنفین جمع ہونے شروع ہوئے___ ڈھیلی ڈھیلی پتلونیں۔ لمبے لمبے بال___ سیاہ فریم کی عینکیں۔ انگلیوں میں پائپ یا سگریٹ اور کھدر کے پاجامے۔
اور جب چائے ختم ہوئی تو جہلم پاکے ایک نوگرفتار لفٹننٹ بولے ۔’’جی کچھ گانا شانا نہیں ہونا ہے۔؟‘‘ اس پر ایک ترقی پسند ادیب نے میری خالہ زاد بہن فرخندہؔ سے فرمایا۔ ’’جی آپ لاہور سے آئے ہیں۔ ایک آدھ ڈھولک کا گیت سنا دیں۔ یہ ڈھولک کے گیت کس قدر حسین اور ستارہ بار ہوتے ہیں۔‘‘ اور میرا جی چاہا کہ اس کی اس سرخ اور لمبی ناک پر ساری چائے دانی انڈیل دوں۔
اتنے میں ہال کے دوسرے سرے میں نئے ادب کی افادیت پر نہایت شدومد سے بحث شروع ہوگئی۔ پیامؔ مرغی شہری فرما رہے تھے ’’جناب ہم ترقی پسند نوجوانوں نے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی اور ہماری خوب صورت نظموں اور افسانوں نے اردو کے دقیانوسی اور سرمایہ داروں کے ادب میں ایک انقلاب پیدا کردیا۔ ہمارا ایک نوجوان شاعر اپنی ایک بلند پایہ نظم میں کہتا ہے ؎
یہ کس نے لاش پھینک دی جوانیوں کی راہ میں
بڑھے چلو، بڑھے چلو ، تباہیوں کی راہ میں
علی جرارصابری نے ارشاد کیا۔ اسی کے متعلق میں نے کہا ہے کہ ؎
مسرت کے جواں ملاح کشتی لے کے نکلے ہیں
غموں کے ناخدائوں کا سفینہ ڈگمگاتا ہے
خالو جان بے چارے خاموش بیٹھے سگار پی رہے تھے۔ پیام مرغی شہری نے پھر کہنا شروع کیا___ ’’تو گویا کہ کامریڈز___ ’’ادب برائے حیات‘‘ نے دنیا پر ثابت کردیا کہ اب ہندوستان کو اس ادب کی ضرورت نہیں جو سرمایہ داروں کے سجے ہوئے ایوانوں میں جنم لیتا ہے ۔ بلکہ اب ہمیں ایسا ادب چاہئے جو جنتا کی دل کی دھڑکنوں کا آئینہ دار اور مزدوروں کے اندھیرے جھونپڑوں کا باسی ہو۔ اور جو جیل کی آ ہنی سلاخوں کے پیچھے چھپی ہوئی مضطرب چیخوں کی نمائندگی کرسکے___ ‘‘ اتنے میں ڈبلیو ، اے ، سی کی ایک اینگلو انڈین لڑکی نے پیامؔ صاحب کو آئس کریم پیش کی ۔ اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوگئے۔ ’’کافی ہائوس‘‘ کا آرکیسٹرا تیزی کے ساتھ بج رہا تھا۔
ہال کے ستون کی دوسری طرف ایک نہایت ترقی پسند افسانہ نگار عظمتؔ چنگیزی خالو جان سے باتیں کر نے میں مصروف تھے۔ اور وہ بے چارے بھی ان سے ’’نئے ادب‘‘ پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے ۔ پام کے گملوں کے پیچھے ہال کے ایک گوشے میں فرخندہؔ اور پدماؔ میرے ساتھ بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں دو ترقی پسند ادیب ہمارے قریب کی میز پر آکر بیٹھ گئے___ ان کے نام مجھے یاد نہیں آرہے___ اور ان میں سے ایک نے فرخندہؔ سے پوچھا۔ ’’آپ نے میرے تازہ ترین افسانے ’’پیٹی کوٹ‘‘ اور ’’توہین‘‘ ملاحظہ فرمائے ہوں گے؟‘‘۔ فرخندہ نے صاف جھوٹ بول دیا۔ ’’جی ہاں بہت عمدہ ہیںوہ‘‘۔ حالانکہ خالوجان کے ساتھ بچپن سے انگلستان میں رہنے کی وجہ سے اس کو اچھی طرح اردو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ دوسرے ادیب نے مجھ پر عنایت کی۔ ’’جی آپ نے ’’چھپر‘‘ تو ضرور پڑھا ہوگا؟‘‘ گویا میری زندگی کا واحد مقصد’’چھپر‘‘ پڑھنا ہی تھا۔ لیکن مجھے بھی فرخندہ کی تقلید کرنی پڑی۔‘‘ آپ کے افسانے تو مجھے بہت پسند ہیں۔‘‘ اور اب انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ’’بات یہ ہے محترمہ کہ ادب اور زندگی کے متعلق میرا تخیل طوفانی راتوں میں ایک جھونپڑے میں رکھے ہوئے ٹمٹماتے چراغ کے مانند ہے۔ کھیتوں کی پگڈنڈیاں۔ گلیوں کی کچی دیواروں کے سائے۔ پنگھٹ کے کنارے۔ ان تمام چیزوں میں سیکڑوں ترقی پسند افسانے پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ میرے سنہری حاشیوں والے دھندلے دھندلے خواب خاموش پتواروں کے پاس جنم لے کر کہانیوں کی شکل اختیار کرلیتے ہیں___‘‘
میں ان کی اس تقریر کوسمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پرویزؔ رومانی ہماری طرف آتے نظرآئے۔ اورقریب آکر کہنے لگے۔’’اوہو! اس آتشیں کتاب ’’شرارے‘‘ کے مصنفین ابھی تک نہیں آئے۔ ٹھیریئے میں فون کرتا ہوں___ ‘‘ اور پام کے گملوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ترقی پسند شاعر نے گنگنانا شروع کیا۔
یہ کس نے فون پر دی سال نو کی تہنیت مجھ کو
تمنا رقص کرتی ہے تخیل گنگناتا ہے
اور ان کے ایک ’’کامریڈ‘‘ نے پرویزؔ صاحب سے کہا۔ ہمارے ان شعلہ بیان مصنفوں میں سے آج شاید کوئی بھی نہ آسکے گا۔ کیونکہ ان میں سے ایک کو تو گورنمنٹ آف انڈیا میں ایک اعلیٰ عہدہ مل گیا ہے اور باقی ہندوستان کو آزاد کرانے میں مصروف ہیں۔‘‘
ہم سے کچھ دور کیپٹن و بیگم قریشیؔ بیٹھی تھیں۔ ہم اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے۔ بدقسمتی سے چار پانچ کمیونسٹ اور اشتراکی قسم کے ادیب وہاں بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کیپٹن قریشی سے کہہ رہے تھے۔’’یہی وجہ ہے کیپٹن صاحب کہ اب ہم زندگی کو ہر ترقی پسند زاویۂ نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہماری جنتا کو اس وقت ’’پیٹی کوٹ‘‘ اور ’’رضائی‘‘ وغیرہ قسم کے حسین افسانوں کی بے حد ضرورت ہے___‘‘اور جب وہ اپنا پائپ جلانے کے لیے رکے تو دوسرے ادیب نے کہنا شروع کیا۔ ’’ قصہ مختصر یہ کہ ہم ایک ایسے سنسار کے باسی ہیں جہاں بھوک ہے ۔ محنت ہے۔ افلاس ہے۔ ظلم وستم ہے ۔ حکومت کا استبداد ہے۔ آنسو ہیں اور آہیں ہیں۔ ہمارے نوجوان شعرا بھی اسی دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں پیامؔ مرغی شہری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی معرکۃ ا لآرا نظم ؎
سرخ و سیہ صدیوں کے سائے تلے
آدم و حوا کی اولاد پر کیا گزری ہے
سنا کر ہمیں محظوظ کریں___‘‘ لیکن پیامؔ صاحب میزبان سے اجازت لیے بغیر شاید مس مارگریٹ رولینڈ کے ساتھ سنیما دیکھنے جاچکے تھے۔ اس لیے ان ادیب صاحب نے خود ہی اپنی ایک شاہکار نظم پڑھنی شروع کی ؎
دوپہر کی گرم لُو میں زرد پتیاں ویران سڑکوں پر یوں
اڑ رہی ہیں جیسے
میرے بھولے ہوئے خواب
یا کسی بھوکے مزدور کی آہیں جو
پانی کے نل کے پاس بیٹھا باسی چنے کھارہا ہے۔
میرے سر میں ہلکا ہلکا درد پھر ہونے لگا تھا___ ’’واہ واہ‘‘ کے شور سے ہال گونج اٹھا۔ پھر ایک اور شاعر نے جو اب تک آرکیسٹرا میں پیانو بجانے والی لڑکی کے ساتھ بیٹھے کافی پی رہے تھے، اپنی نظم سنائی ؎
خوابوں کے دھندلے جزیروں کے اس پار
دور شفق کے رنگین کناروں میں کھوئے ہوئے خیالوں کی طرح
جب کلاس روم میں خاموش بیٹھا ہوتا ہوں میں
تو باہر گھاس کھودنے والی مزدور لڑکی کی چوڑیوں کی جھنکار
سن کر مجھے
غلام آباد ہندوستان کا خیال آتا ہے اے دوست
اور میں سوچتا ہوں کہ بپا کروں
ایک خونی انقلاب
یا پھر جمنا کی بے تاب لہروں کو چیر کے
افق سے جاٹکرائوں
نوکری ملتی نہیں ہے مجھ کو اس لیے
نئے ادب کی شاعری کا عارضہ ہوا
ہے لاحق
کاش میں ہوسکتا داخل ایمرجنسی کمیشن میں
گرنہ ہوتا مجھے خیال اے دوست تیرا
میرے سر میں درد بہت زور سے شروع ہوگیا ۔ میں نے پریشان ہوکر ممی کو دیکھا اور میزبان سے معذرت چاہ کے باہر کار میں آکر لیٹ گئی اور اس رات خواب میں مجھے یہ معلوم ہوا جیسے بہت سے ترقی پسند ادیب اپنے حسین افسانوں اور خوب صورت نظموں سمیت میرے کمرے پر دھاوا کر رہے ہیں۔ تاکہ جنتا کی حالت سدھرے ۔ اور غلام آباد ہندوستان کو آزادی نصیب ہوجائے۔
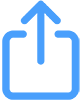 then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'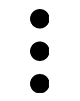 then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'





کوئی تبصرہ نہیں