اردو ادب کی تشکیل جدیدکا مسئلہ
تاریخ بتاتی ہے کہ محکوم قوم حاکم قوم کی پیروی کے لیے تمام شعبہ ہائے حیات میں نفسیاتی طور پر خود کو مجبور پاتی ہے۔ یہ بات مزید دو آتشہ اس وقت ہوجاتی ہے جب کہ حاکم اپنے اقتدار کی توسیع و بقا کے لیے اپنے سیاسی، سماجی او رمعاشی منصوبوں کو محکوم کے سامنے خیرخواہی کے لبادہ میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر محکوم قوم کے سامنے ایسا علمیاتی زاویہ فراہم ہوجاتا ہے جس کے تناظر میں وہ اشیا اور کائنات کے مطالعہ کو دانشمندی قرار دیتا ہے۔ مغرب کے حوالے سے اگر اس پہلو کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مغرب نے خود کو سیاسی،ثقافتی اور ادبی قوت کے استعمار کے طور پر ہندوستانیوں کے ذہن میں جاگزیں کیا۔
زیرمطالعہ کتاب اردو ادب کی تشکیل جدید، ان مصنفوں اور دانشوروں کے مطالعہ پر مشتمل ہے جنھوں نے جدید اردو دادب کی تعمیر وتشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ مصنف نے سرسید، حالی، شبلی، نذیراحمد، اکبر الہ آبادی، منٹو،میراجی، قرۃ العین حیدر اور انتظارحسین کی تخلیقات کواپنے موقف کی توثیق کے لیے منتخب کیا ہے۔ مذکورہ مصنّفین میں سے سرسید، حالی، شبلی، نذیراحمد، اکبرالہ آبادی کا مطالعہ نو آبادیاتی نظریے کے تحت اور منٹو، میراجی، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین کی تخلیقات کا پس نوآبادیاتی نظریے کے تحت جائزہ لیا گیا ہے۔
زیرنظر کتاب کے عنوان سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ کتاب اردو کے مکمل جدید ادب کی تشکیل و تعبیر کو محیط ہوگی لیکن امرواقعہ اس کے برعکس ہے۔ مصنف نے اردو ادب کے کچھ ناموں کا انتخاب کرکے ان کے ادبی تصورات کوتعمیمی انداز میں پورے ادب پر حاوی ثابت کرنے کی سعی کی ہے جو سائنٹفک طریقہ کار سے میل نہیں کھاتا۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ ۱۸۵۷ء کے رستخیز حالات نے اس عہد کے نابغوں سرسید، حالی، محمدحسین آزاد، شبلی کو مغرب کی بالادستی تسلیم کرنے کے لیے مجبور کردیا تھا۔ ان تمام افراد نے اپنے اپنے مبلغ علم اور دور اندیشی کے اعتبار سے مغرب کو قبول کرنے کا رویہ اختیار کیا۔ تاہم مغرب کو قبول کرنے میں یہ لوگ یکساں روی کا مظاہرہ نہیں کرتے ۔ سرسید کے یہاں مغرب سے اثرپذیری کا جو انداز ملتا ہے وہ اس عہد کے دیگر ارباب نظر سے مختلف ہے۔ کیوں کہ انھوں نے مغربی نظام کا مطالعہ اس سسٹم کا حصہ بنے رہنے کے بعد کیا تھا۔ یہی حال حالی اور ڈپٹی نذیراحمد کا تھا ۔ ان بزرگوں نے دلی کے دور عروج کو بھی دیکھا تھا اور زوال کو بھی بھگتا۔ شہزادے ، شہزادیوں کی محتاجگی دیکھی، نان شبینہ کے لیے ترستے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا جن کے دسترخوان سے ایک عالم سیراب ہوتا تھا۔ ان حضرات کی مغرب پرستی شبلی سے علیحدہ ہے۔ شبلی نے ۱۸۵۷ء کے روح فرسا حالات کا مطالعہ قدرے زمانی فاصلہ سے کیا تھا لیکن ان تمام حضرات میں قدرمشترک یہ ہے کہ یہ لوگ مغربی عظمت کے قائل اور وکیل ہیں۔ ناصرعباس نیر نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ لوگ نوآبادیاتی ایجنڈے کی توسیع کے لیے آلہ کار بنے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان ارباب علم و ہنر کے وجود کی بقا کا مسئلہ تھا۔
ناصر عباس نیر ایسا بیانیہ وضع کرنے کے مدعی ہیں جو استعماری نظام کی تردید کرتا ہے جسے وہ متبادل بیانیہ کا نام دیتے ہیں۔ انھوں نے متبادل بیانیہ کے جن خصائص کی نشاندہی کی ہے، اس کے اہم نکات ملاحظہ کیجئے:
ردنوآبادیات کے لیے متبادل بیانیہ کی تخلیق لازمی ہے۔ ’’اگرردنوآبادیات سے مراد یہ ہے کہ سفیدآدمی و سفید کلچر کے خارجی وسیاسی استحصال اور داخلی ونفسیاتی جبر سے نجات حاصل کی جائے تو یہ حقیقی متبادل بیانیے کی تخلیق ہی سے ممکن ہے۔(پیش لفظ، ڈ)
احتجاجی، مزاحمتی اور قومی بیانیہ متبادل بیانیہ ہی کے قبیل سے ہے مگر دونوں میں فرق ہے۔ احتجاج ومزاحمتی بیانیہ استعمار کار کے بیانیہ پرمنحصر ہوتے ہیں جب کہ متبادل بیانیہ استعمارکار کے حاوی بیانیوں پرلازمی انحصار سے آزاد ہوتا ہے… متبادل بیانیے کا آغاز اپنے وجود کے مستند اظہار اپنی زبان اپنی ثقافت کی بازیافت کی آرزو سے ہوتا ہے……متبادل بیانیہ سب سے پہلے زبان کو اس مصنوعی و تشکیلی حقیقت سے آزادکراتاہے جسے استعماری لسانی پالیسی اور اس کی نظریاتی ترجیحات نے وضع کیا ہوتا ہے۔متباد ل بیانیہ کا نتیجہ ایک متن ہوتا ہے،ایک ایسا متن جو ان سب متون کے دعوؤں کو تہہ و بالا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے جنھیں استعمار کار نے کنین کا درجہ دے کرسماج میں رائج و مقبول کیا ہوتا ہے… متبادل بیانیہ آزادی بخش ہوتا ہے… متبادل بیانیہ استعمار زدہ طبقے کا وہ بیانیہ ہے جو استعمار کار کے بیانیوں کے متوازی پیش کیا جاتا ہے۔ آخرالذکر بیانیے استعمار زدہ لوگوںکے علم، کلچر، ادب، تاریخ سب کو میثل فوکو کے مطابق ، محکوم و سرنگوں علم کے طور پر پیش کرتے ہیں یعنی وہ علم جو علوم کی درجہ بندی میںنچلے درجے پر ہے اور شعور اورسائنسیت کے مطلوبہ معیار سے فروتر ہے۔ متبادل بیانیہ اس سرنگوں علم کوسربلندکرتا ہے ۔‘‘ (پیش لفظ، ڑ)
متبادل بیانیہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وہ تحریر کرتے ہیں کہ :متبادل بیانیہ:
’’علم کی اس درجہ بندی پر سوالیہ نشان لگاتا ہے جسے مقتدر طبقے یا مقتدر علمیات نے قائم کیا ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ شعور اور سائنسیت کے مطلوبہ معیار کو ایک ایسی تشکیل ثابت کرتا ہے جسے حاکمانہ آئیڈیالوجی نے وضع کیا ہوتا ہے۔ گویا حاوی اور غلبہ پسند بیانیے کے معیارات کے متوازی نئے معیارات قائم کرنے والا بیانیہ متبادل بیانیہ ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو مسلسل باور کراتا ہے کہ حاوی اقتداری بیانیوں کے متبادلات کی تخلیق ممکن ہے۔‘‘ (پیش لفظ،ژ)
ناصر عباس نیر مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں ایسا متبادل بیانیہ وضع کرنے کے مدعی ہیں جو پس نوآبادیاتی تنقید کا متبادل ہوسکتا ہے۔متبادل بیانیہ پر کئی اعتراضات وارد کیے جاسکتے ہیں:
(۱) متبادل بیانیہ کا نظریاتی پہلو بھی مزاحمانہ عنصر سے عاری نہیں ہوتا۔
(۲) مصنوعی و تشکیلی حقیقت سے آزاد کرانے کا طریقہ کار کیا ہوگا جب کہ مصنف ہی کا قول ہے کہ ’ایک زبان کی ساخت میں جذب ہونے والے کسی دوسری زبان کے اثرات کو یک قلم نکالا نہیں جاسکتا۔‘
(۳) ثقافت کی بازیافت کی آرزو کیاماضی پرستی نہیں ہے۔
(۴) بازیافت اور احیا کے درمیان کی تفریق التباسی نوعیت کی ہے۔ مصنف کی اصطلاح میں بات کی جائے تو کہاجاسکتا ہے کہ بازیافت پہلا زینہ ہے احیاء کا۔
(۵) متبادل بیانیہ کے مرکز میں بھی استعمار کار حاوی بیانیہ کے طور پر بہرحال موجود ہوگا۔
(۶) آپ کا متبادل بیانیہ غیرسیاسی نہیں ہوسکتا۔ سیاسی تعبیر ہمیشہ متعلقہ مقتدرہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔
(۷) متبادل بیانیہ کے اطلاقی پہلو میں مناظرانہ نثر (Polemic Prose)کا غلبہ ہے جو آپ کے متبادل بیانیہ کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ ۱۸۵۷ء کے ارباب حل و عقد استعماری سازشوں کا مکمل ادراک رکھتے تھے، موقع بہ موقع اس کی تردید کرتے رہتے تھے،جس کا اظہار ذیل کے اقتباسات سے ہوتا ہے۔
حالی لکھتے ہیں:
’’بات یہ ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصے نے علم و ہنر میں اس قدر ترقی کی ہے اور وہ دوسرے حصے کے ابنائے جنس سے اس قدر آگے بڑ ھ گیا ہے کہ اگلے زمانے کے فاتح اور کشور کشا جن ناجائز ذریعوں سے مفتوحین کی دولت و ثروت اور سلطنت کے مالک ہوتے تھے، ان ذریعوں کے کام میں لانے کی اب مطلق ضرورت نہیںرہی جس قدر مال و دولت پہلے قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ سے حاصل کیا جاتا تھا، اس سے اضعاف مضاعفہ اب صنعت و تجارت کے ذریعہ سے خودبخود کھینچا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب دو ایسی گورنمنٹوں کے درمیان جن میں سے ایک شائستہ اور دوسری ناشائستہ ہو تجارتی عہد نامہ تحریر ہوجاتا ہے تو یقینا یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شائستہ گورنمنٹ بغیر اس کے کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری دوسری گورنمنٹ کے تمام ملک و دولت و منافع محاصل کی بالکل مالک ہوگئی۔‘‘(مقالات حالی، حصہ اول، ص:۴۴)
شبلی اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں:
’’یورپ نے کسی زمانے میں مسلمانوں کے خلاف جو خیالات قائم کرلیے تھے ایک مدت تک وہ علانیہ اس طریقہ سے ظاہر کیے جاتے تھے کہ مذہبی تعصب کا رنگ صاف نظر آتا تھا۔ لیکن جب یورپ میں مذہب کا زور گھٹ گیا اور مذہبی ترانے بالکل بے اثر ہوگئے تو اس پالیسی نے دوسرا پہلو بدلا اب یہ طریقہ چنداں مفید نہیں سمجھا جاتا کہ مسلمانوں کی نسبت صاف صاف متعصبانہ الفاظ لکھے جائیں بلکہ بجائے اس کے یہ دانش مندانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومتوں، اسلامی قوموں، اسلامی معاشرت کے عیوب تاریخی پیرایے میں ظاہر کیے جاتے ہیں اور عام تصنیفات، قصوں، ناولوں، ضرب المثلوں کے ذریعہ وہ لٹریچر میں اس طرح جذب ہوجاتے ہیں کہ تحلیل کیمیاوی سے بھی جدا نہیں ہوسکتے۔ یورپ میں مصنفین کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس وجہ سے ان میں متعصب، نیک دل، ظاہر بیں، دقیق النظر، ہردرجے اور ہر طبقے کے لوگ ہیں لیکن ترکوں کے ذکر میں وہ اختلاف مدارج بالکل زائل ہوجاتا ہے۔‘‘(سفرنامہ روم ومصرو شام، ص:۱۴)
حالی کی قومی شاعری او راکبر الہ آبادی کی ظریفانہ شاعری اور اس نوع کی تحریریں کیا متبادل بیانیہ کے ذیل میں شامل نہیں کی جاسکتی ہیں۔
حالی کامذکورہ اقتباس کیا حاوی اور غلبہ پسند بیانیے کے مضمرات کی نقاب کشائی نہیں کرتا؟ کیا پولیٹیکل اکانومی کا ادراک حالی کا کارنامہ نہیں ہے۔ یہ اس دور میں لکھا ہوا مضمون ہے جب کہ ہر طرح کی تحریروں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ یہ وہ حالی تھے جو انگریزی حکومت کے ملازم تھے۔
شبلی کا مذکورہ اقتباس بھی ’’تاریخ و ثقافت و ادب کی تعبیر پر غالب آنے والی استعماری، علمیاتی اغراض کو منکشف کرتا ہے۔‘‘
ناصرصاحب نے قومی ادب اور قومی شاعری کو انگریز حکمرانوں کے لیے ایک گنج گراں مایہ قرار دیا ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں ’’لوک داستانیں ہندوستان کی اس نئی اجتماعی سائیکی کی ترجمان نہیں تھیں جو یورپی اثرات کے نتیجے میں صورت پذیر ہورہی تھی۔ علاوہ ازیں وہ نئے قومی ادب کے ذریعہ نئی حسیت بھی پید اکرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو اسکول کی نصابی کتاب تیار کرنے سے مختلف تھا، جہاں یہ ہیں تو اسی لکیر پر ہمارے شاعر چلے اور کہیں انھوں نے اسی ادب کویورپی حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کا ذریعہ بنایا۔‘‘ (ص:۴۸)
سوال یہ ہے کہ کیااحتجاج آزادی کی جانب پہلا قدم نہیں ہوتا؟ کیا مزاحمتی بیانیوں کی شدت کو صرف یہ کہہ کر کم کیا جائے کہ اس کی ابتدا، اس کی سمت، اس کی حد استعمار کار کے بیانیوں سے طے ہوتی ہے (پیش لفظ)۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ جب استعمار زدہ اقوام، نوآبادکار کی سازشوں کا ادراک کرتا ہے تو وہ یا تو ماضی میں پناہ لیتا ہے یا احتجاج کرتا ہے یا کلی طور پر استعماری نظام کو قبول کرلیتا ہے یا ادغام کی کوئی صورت معرض وجود میں آتی ہے اور ہر صورت میں نوآبادکار کے مفاد کو استحکام ملتا ہے۔ میراعندیہ یہ ہے کہ کیا استعمار زدہ اقوام کے سامنے اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ بچتا ہے۔ دراصل مقتدرہ کے لیے قوت کی ہمہ گیری کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ باور کراتا ہے استعمار زدہ قوم کا ہر عمل اس کے حدود میں ہے اور اس کے مفاد کو مستحکم کرنے کا باعث ہے تاکہ استعمار زدہ قوم نفسیاتی طور پر بے بس ہوکر ردعمل کی بھی جرات نہ کرسکے۔
ناصرصاحب، سرسید، حالی، شبلی اور اکبرالہ آبادی کے افکار و تصورات کے مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ حضرات ایک طرف مغربی افکار کی وکالت بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کی تنقیص بھی کرتے ہیں۔ امرواقعہ یہ ہے کہ جب وہ حضرات مغرب کی وکالت، تحسین یا تائید کرتے ہیں تو اس مغرب کا اعتراف کرتے ہیں جو علمی ترقی سے عبارت ہے۔ ایجادات و انکشافات کا حامل ہے اور جب تنقیص کرتے ہیں تو اس مغرب کی جو ظالم ہے، جو عسکری قوت کی بنا پر قوموں کی آزادی ہڑپ کرلیتا ہے سیاسی اور مالی استحصال کرتا ہے، دیگر قوموں کے علمی ورثے کو سبوتاژ کرتا ہے۔ کیا ان حضرات کی کاوشوں کو عین علمی اور دیانتداری پر مبنی نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیا ان حضرات کے مغرب سے استفادہ کو وہ رویہ نہیں قرار دیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں ناصر صاحب رقم طراز ہیں کہ :
’’فلسفہ و سائنس نہ یوروپی ہیں نہ مشرقی، یہ انسانی مساعی ہیں اور انسانیت کی مشترکہ وراثت ہیں۔ لہٰذا فلسفہ یورپ میں پیدا ہوا ہو یا چین و ہندوستان میں وہ مطلق نظری بصیرتوں کا حامل ہوتا ہے۔ جہاں تک ان بصیرتوں میں اختلاف کا سوال ہے تو وہ فلسفیوں کے مابین ہوتا ہے۔ مشرق و مغرب کے مابین نہیں۔‘‘ (ص:۱۸۸)
ناصرعباس نیرکی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ تعبیر کے تمام حربوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ حاکم و محکوم کے درمیان مشرق و مغرب کے درمیان انگریز اور ہندوستانیوں کے درمیان کے تمام معاملات خواہ وہ علمی ہو سیاسی ہو یا ثقافتی ہو، ناصر سب کا تجزیہ اور تعبیر مقتدرہ کے تناظر میں کرتے ہیں۔ کیا یہ نقطہ نظر کسی صحیح نتیجہ تک ہماری رہنمائی کرسکتا ہے۔ سرسید، حالی، شبلی، نذیراور اکبرالہ آبادی کے افکار و تصورات کا مطالعہ جس طرح ناصر کرتے ہیں اس سے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ ان سب کی بنیاد مکمل طور پر مغربی فکر پر استوار ہے۔ ناصر کے طر زمطالعہ سے اپنے اسلاف کے تئیں حقارت، ان کی بے بضاعتی اور کم مائیگی کا احساس ہمارے دلوں میں جاگزیں ہوجاتا ہے جو نوآبادیاتی مقتدرہ کا مطمح نظر تھا۔
شبلی کے سلسلے میں ناصرصاحب کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے:
’’پہلی نظر میں شبلی کا رویہ محض ایک انصاف پسندانہ علمی رویہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی معروض کی خرابیوں کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیو ںکا بھی اعتراف کیا جائے۔ لیکن جب ہم اس علمی رویے کا مطالعہ نوآبادیاتی سیاق میں کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ یہ ایک نئی حسیت اور نئی علمیات ہے: تضاد کو بہ یک وقت گرفت میں لینے کی حسیت اور جدلیاتی تصور کے تحت معنی یابی کی علمیات نیز ایک ایسی طاقت سے معاملے کی حکمت عملی بھی ہے، جو اردو گرد یہاں وہاں تعلیم و ثقافت، سیاست، زبان، زبانوں کی درجہ بندی، ذرائع ابلاغ، عمارتوں، دفتروں، اداروں، کتابوں بیانیوں کی صورت موجود ہے اور چھاجانے کی غیرمعمولی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ طاقت فاصلہ پسند کرتی ہے… دوسرے لفظوں میں یورپ نمائندگی کا ایک ہشت پہلو نظام تھا۔‘‘ (ص:۳۲۷)
اس اقتباس سے اگر نوآبادیاتی سیاق کو منہا کردیا جائے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان مندرجات کا صدفی صد اطلاق خود ناصرعباس نیر کی تحریر پر ہوتا ہے وہ اپنے معروض کی پیشکش میںجدلیاتی طریقۂ کار کا استعمال کرتے ہیں۔
اردو میں پس نوآبادیاتی مباحثہ کا آغاز مغربی مفکرین ایڈورڈ سعید اورفرانزفینن ہی کی تحریروں سے تسلیم کیا جاتا ہے یہ بات توجہ طلب ہے کہ کیا اردو ادب میں استعماری بیانیوں سے نجات حاصل کرنے کی کاوش مغربی مفکرین کا مرہون ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پس نوآبادیاتی تنقید کے بھی وہی نتائج آخری مراحل میں برآمد ہوتے ہیں جو نوآبادیاتی فکریات کے تھے یعنی اپنے اسلاف کو حقیر سمجھنے کا رویہ اور اردو ادب کی علمی بنیادوں کو مغرب سے مستفاد و مستعار باور کرانے پر اصرار۔
ناصرعباس نیر Historicismکے مضمرات سے بخوبی واقف ہیں۔وہ تعبیر و تشریح کے ان تمام حربوں سے آگاہ ہیں جن میں تاریخی محرکات، سماجی اسباب و علل اور عمرانیاتی حوالوں کی مدد سے اپنے موقف کے لیے قاری کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرسید،حالی، شبلی سے متعلق جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں ان سے نتائج کے استخراج میں ا س عہد کی حرکیات و ارتعاشات کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔
ناصرصاحب نے ڈپٹی نذیراحمد کے ناول ’توبۃ النصوح‘ کو ڈینیل ڈیفو کے ناول The family instructorسے مستفاد قرار دیا ہے اور توبۃ النصوح کو عیسائی روح کا حامل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں عیسائیت سے متاثر قرار دینے کے لیے جن دلائل کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ’’اس میں گناہ، ندامت اور توبہ کے ان تصورات کی زیرسطح گونج موجود ہے جو عیسائی تصور کائنات میںموجود تھیں۔‘‘ (ص:۹۰) ناصر جیسے دانشمند نقاد پر یہ اعتراض سرسری معلوم ہوتا ہے لیکن انھوں نے ان تصورات کی جو تاویل پیش کی ہے وہ توبۃ النصوح کے مزاج سے میل نہیں کھاتی ہے۔
نصوح کلیم کے نام خط میں یہ کہتا ہے ’’الغرض ہر گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے اور جو شخص اس گھر میں بڑا بوڑھا ہے وہ اس میں بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور گھر کے دوسرے لوگ بہ طور رعایا اس کے محکوم ہیں۔ (ص:۹۲)
مصنف اس اقتباس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ ’’نصوح نہ صرف اپنے اختیار کا تصور ایک ریاستی سربراہ کے طو رپر کرتا ہے بلکہ اس اختیار کو بروئے کار لانے کے لیے اسی طریق کار کو جائز سمجھتا ہے جسے نوآبادیاتی حکمرانوں نے ہندوستانیوں کے لیے روا سمجھا تھا۔‘‘
۱۸۵۷ء کے پرآشوب حالات کے بعد مسلمانوں میں اصلاحی فکر کا بیدار ہونا فطری ہے۔ اس ضمن میں نصوح اپنی غفلت کو مفلوک الحال ریاست کے حاکموں کی طرح قرار دیتا ہے۔ اس سیاسی تمثیل کو نوآبادیاتی قرار دینا محل نظر ہے۔ توبۃالنصوح میں ڈپٹی نذیراحمد نے کلیم کی کتابوں کو جلانے کے جواز کے طور پر یہ کہا ہے کہ یہ کتابیں سانپ کی طرح موذی ہیں۔ ناصرعباس نیراپنی ہمہ دانی اور بحرالعلومی طریقہ کار کے ساتھ حاضر ہوجاتے ہیں۔ سانپ سے متعلق عیسوی تصور، مشرقی تصور، ہندی اساطیری تصور کی تفصیل بیان کرتے ہیں پھر تمام تناظرات سے منسلک کرکے معنی کی جہت منور کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ یہ طرز تعبیر متن سے من مانا معنی مستخرج کرنے کے جواز کا پرفریب حربہ ہے۔حالانکہ معنی تو متعلقہ تصورکائنات کی روشنی میں طے ہوتے ہیں۔
اس کتاب میں دہرے شعور کی کشمکش: سرسید کی جدیدیت اور اکبر کی رداستعماریت کے عنوان سے اس ادغامی وانضمامی صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے جو سرسید اور اکبرالہ آبادی کی تحریروں سے مترشح ہوتا ہے۔ سرسید اور اکبرالہ آبادی دونوں میں مشترک وصف یہ ہے کہ دونوں مغرب اور مشرق کے مابین ایک توازن چاہتے تھے۔ مصنف نے دونوں کے اس رویے کے درمیان ایک امتیازی لکیر بھی کھینچی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سرسید مستقبل شناس اور مغرب کی طرف زیادہ راغب تھے اور اکبر کا حاوی میلان ماضی کی طرف تھا اور ماضی میں مذہب کو شاہ کلید خیال کرتے تھے۔ مصنف نے اس عہد کے ادغامی رجحان کو دہرے شعور سے تعبیر کیا ہے۔ محمدحسین آزاد، حالی، سرسید اور اکبرالہ آبادی کے انگریزی حکومت میں برسرروزگار ہونے پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
’’یہ سب ہندوسانی تھے، مسلمان تھے، ان کی وضع اس ہند اسلامی تہذیب کی مرہون تھی جس کا بڑا مرکز دہلی تھا اور اب انگریز سرکار کی رعایا اور ا ن کے نمک خوار تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ان سب باتوں سے آگاہ تھے۔ انھیں اپنی اس ذات کی آگاہی حاصل تھی، جس کاثقافتی تانا سیاسی بانے سے جدا تھا۔ وہ ایک معزول ثقافت کی پیداوار اور ایک نئی سیاسی شہریت کے حامل تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سب دہرے شعور کے حامل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید اردو ادب کی اگر کوئی واحد اصل ہوسکتی ہے تو وہ یہی دہرا شعور ہے۔‘‘ (ص:۱۳۲)
آگے چل کر مصنف دہرے شعور کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ’’دہرے شعور سے متعلق دوسری اہم بات یہ ہے کہ دہرا شعور، شعور کا انتشار نہیں شعور کی کشمکش ہے…
اگر دہرے شعور سے مراد شعورکی کشمکش ہے تو یہ کشمکش روشن خیال یورپ اور استعمار یورپ کی تحسین اور تنقیص کے درمیان ہے ۔جیسا کہ دادا بھائی نوروجی کے حوالے سے ناصر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ : ’’ہندوستان کو جدید یورپ کی ضرورت ہے مگر اسے استعماری یورپ کا سامنا ہے۔ ان کی نظر میں ہندوستان کی حالت اس بچے کی سی ہے جسے والدین مٹھائی دیتے ہیں مگر بچے کے لیے اس کے خالی پیٹ ہونے کی بنا پر یہی مٹھائی زہربن جاتی ہے۔‘‘(ص:۱۸۷)
ناصرعباس نیر کا کہنا ہے کہ (اس عہد میں) استعماریت اور روشن خیالی، مغربیت اور جدیدیت میں فرق کرنا مشکل تھا۔(ص:۱۷۲) پھر یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا یہ لکیر اکبر کو نظر آرہی تھی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ پیشہ ورانہ، عملی تعلیم کے حامی تھے تو یہی رائے قائم کریں گے کہ انھیں مغربی وضع کی نقل اور نئے علوم کی تحصیل کا فرق معلوم تھامگر کیا واقعی؟ (ص۱۷۲) میرا خیال ہے کہ مصنف نے جو دہرا شعور اور دو جذبیت کی اصطلاح استعمال کی ہے، اس کی یہی تعبیر ہونی چاہیے کہ اس عہد کی یہ عبقری شخصیتیں استعماریت اور روشن خیالی کے فرق سے بخوبی واقف تھیں۔ یہی سبب ہے کہ اس عہد کی علمیات کو اگر کسی ایک اصطلاح میں سمیٹا جاسکتا ہے تو وہ امتزاج کی اصطلاح ہوگی۔ یہ انضمام یورپ کی روشن خیالی اور مشرق کے درمیان تھا۔
کتاب میں اکبرالہ آبادی کی استعمار شناسی اور ان کے تردیدی طریقہ کار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے لیکن ان کے کارناموں کی شدت کی تخفیف کی غرض سے انھیں دہرے شعورکے زمرے میں رکھ کر اس کی اصل کو مغرب سے فیض پذیری کا ثمرہ قرار دے دیا گیا ہے۔
ناصرعباس نیر لکھتے ہیں کہ:’’ استعمار کے خلاف عملی و فکری مزاحمت کا آغاز مذہبی طبقات کی طرف سے ہوا۔ اس کے بعد جدید تعلیم یافتہ بنگالیوں کی جانب سے ص(۱۹۲) یہ خوش گوار حیرت کی بات ہے کہ ناصر نے رداستعماریت کے سلسلے میں مذہبی طبقات کی جانب سے انجام دیے گئے کارناموںکی اولیت کا اعتراف کیا۔ لیکن اس موضوع پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی اور اس جہان سے سرسری گزرگئے۔ سیداحمدشہیدکی پوری تحریک استعمار مخالف تھی، دارالعلوم دیوبند کے قیام کی بنیاد استعماری مہم کے خلاف ڈالی گئی تھی۔ ریشمی رومال کی تحریک اور خلافت تحریک کی اساس رد استعماریت پر تھی۔ ماضی قریب میں دارالمصنفین اعظم گڑھ کی جانب سے سن ۱۹۸۲ء میں اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے ایک بین الاقوامی سمینار کاانعقاد کیا گیا، جس کے مقالات سات جلدوں میں منظرعام پر آچکے ہیں۔
زیرمطالعہ کتاب میں ماضی کی بازیافت کے حوالے سے مشرق کے ان نابغوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے مشرق کی روشن خیالی عبارت ہے۔ اس عہد کا ذکر ہے جو مشرق کی تعقل پرستی، فلسفہ پر اصرار، سائنسی اکتشافات کے لیے مشہور ہے۔ مصنف، ابوالعلا معری الکندی، ابوبکررازی، عمرخیام، فارابی وغیرہ کے افکار اور ان کے کارناموں کی بازیافت کے خواہاں ضرور ہیں لیکن مشرق کے ان عبقریتوں کے تذکرے کو احیاپرستی قرار دے کر اس کی تخفیف کرتے ہیں۔ مصنف کی اصطلاح کی روشنی میں ان سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا احیا کا عمل بازیافت کی منزل تک پہنچنے کے لیے پہلا اور لازمی زینہ نہیں ہے۔ اکبر کے حوالے سے مصنف نے اسلامائزیشن کے تصور پر گفتگو کی ہے لیکن اس کی وحدانی تعبیر کرکے اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ اس ماحول میں بازیافت کی عملی شکل کیسے ممکن ہے جہاں ماضی کی ایسی تعبیر پیش کی جاتی ہے کہ اسلاف کے کارناموں کے اتباع کرتے ہوئے نئی نسل اس تذبذب کا شکار ہوجاتی ہے کہ کہیں ہمارے اس عمل کے ذریعہ نوآبادیات کو استحکام تو حاصل نہیں ہورہا ہے۔
ناچیز کا موقف ہے کہ پس نوآبادیاتی تنقید بھی نو آبادیاتی فکریات ہی کو مستحکم کرنے کی ایک بالواسطہ کاوش ہے۔ سرسید، حالی، شبلی،محمدحسین آزاد اوراکبرالہ آبادی کی تخلیقات اور ان کے افکار و تصورات کو دہرے شعور اور دو جذبیت کا حامل قرار دے کر ان کی تخفیف کی جارہی ہے۔ ان افراد کے علوم و افکار کو مغرب سے مستفاد ثابت کرکے انھیں کم مایہ اور بے بضاعت قرار دیا جارہا ہے۔ دو جذبیت کے تناظر میں شبلی کی تنقید کا مطالعہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ مطالعہ شبلی کے ضمن میں ناصر کا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے ایک ایسے شبلی کو دریافت کیا ہے جو معنی کی سیاست کا ادراک کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں:
’’بنوامیہ نے جب ظالمانہ حکومت شروع کی تو عرب کی خودسر طبیعتیں گوارا نہ کرسکیں اور بغاوتیں برپا ہوئیں۔ اس کے لیے ایک طرف توحجاج وغیرہ جیسے ظالم مہیا کیے گئے کہ آزادی اور خودسری کو پامال کردیں۔ دوسری طرف مذہبی لوگوں کو رشوتیں دی گئیں کہ قضاوقدر کامسئلہ پھیلائیں یعنی یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے اس کی شکایت خدا کی شکایت ہے۔ اس کے مقابلے میں معتزلہ نے عدل کا مسئلہ اس میں شامل یعنی یہ کہ خدا عادل ہے اور وہ کبھی عدل کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دونوں خیالات ساتھ ساتھ رقیبانہ پھیلے۔ لیکن ادھر تو حکومت کا زور ادھر چوتھی صدی کے آغاز سے آفتاب علم کا شروع ہوا اور اشاعرہ کے خیالات تمام دنیا پر چھاگئے۔ جن سے یہ خیالات پھیلادیے گئے کہ خدا کے لیے عدل ضروری نہیں، بادشاہ خدا کا سایہ ہے۔ بادشاہ کی عزت خدا کی عزت اور اس کی توہین خدا کی توہین ہے۔ ان خیالات نے طبیعتوں کی آزادی، دلیری، راست گوئی، بلند ہمتی کا بالکل خاتمہ کردیا۔ اخلاق پر نہایت اعلیٰ درجہ کی کتابیں لکھی گئیں لیکن اخلاقی مسائل کے عنوان یہ ہیں۔ احسان، تواضع، حلم،عفو، سخاوت، توبہ وغیرہ وغیرہ۔ آزادی اور حق گوئی کا عنوان اخلاقی کتابوں میں نہیں مل سکتا۔‘‘
ناصرصاحب اس اقتباس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:
’’شبلی کو معنی کی اس سیاست کا خیال اتفاقاً نہیں سوجھا۔ انھوںنے خود اسی سیاست کو مستشرقین کی تحریروں میںکارفرما دیکھا تھا۔ نیزعلی گڑھ، جدید تعلیم، روم روس کی جنگ، کانگریس، مسلم لیگ ان سب میںانھوں نے خیالات کی آویزش کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مورخانہ شعور نے بھی معنی و خیال کی آویزش کا مشاہدہ کیا تھا۔‘‘(ص:۳۴۲)
مصنف یہاں پر بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور شبلی کے اس شعور پر مستشرقین کی تحریروں کا عکس تلاش کرلیتے ہیں۔
ناصرعباس نیر شبلی کی ذاتیات پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، جوان کی علمی شان کو زیب نہیں دیتی۔ وہ شیخ اکرام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: ’’شبلی کے باقی سب بھائیوں نے کالجوں میں تعلیم پائی اور وہ اپنے گھر میں جدید کے خلاف قدیم کے ترجمان تھے بلکہ شاید نفسیات کا طالب علم تویہ کہے گا کہ ان کے تحت الشعور میں جدید تعلیم کی نسبت وہی خیالات و جذبات تھے جو اپنے گھر میں سوتیلی والدہ کی نسبت تھے۔ تکمیل تعلیم کے بعد جب انھیں انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے معمولی ملازمتیں بھی نہ ملیں تو انگریزی تعلیم کے خلاف ان کا غم و غصہ اور بڑھ گیا۔‘‘(ص:۳۲۱)
یہ عجیب اتفاق ہے کہ فکشن کے مطالعات کے ضمن میں ناصر صاحب کے معیارات بدل جاتے ہیں وہاں مشرق و مغرب کو طاقت کی حرکیات کے تناظر میں دیکھنے کا رویہ کمزور ہوجاتا ہے۔ مرکز گریز تصور کو اساس بناکر فکشن کے ضمن میں جو مطالعات پیش کیے گئے ہیں ان سب میں استعمار کے علاوہ کسی اور مرکز کا ذکر کیاگیا ہے۔ اس میں استعمار کارسے آزادی کی خواہش کے بجائے موت سے آزادی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اسی طرح لباس سے آزادی کو محور بناکر گفتگو کی گئی ہے۔
فکشن مطالعات کے ضمن میں اردو ادب کے ان شہ پاروں کو بھی مرکز توجہ بنایا جاتا تو بہتر ہوتا جسے ۱۸۵۷ کے زمانے میں انگریزوں نے ضبط کرنے کاحکم صادر کیا تھا۔ ان میں سب سے اہم پریم چند کا افسانوی مجموعہ ’سوزوطن‘ ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت تھی کہ آخر مقتدرہ کو ان تحریروں سے کس قسم کاخطرہ لاحق تھا۔ جب مجموعی طور پر اردو ادب کی تشکیل جدید کامسئلہ ہے تو اس عہد کی صحافت بھی پیش نظر ہونی چاہیے تھی جس پر پابندیاں عائد کی گئیں یاوہ ضبط کی گئیں۔ ان تحریروں میں استعمار کی مخالفت کا کون ساپہلو اختیار کیا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد کی عدم موجودگی بھی تشنگی کا احساس دلاتی ہے۔
ناصرصاحب لکھتے ہیں: ’’لاشعورکی غیر کے کلامیے سے آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ لاشعور سے ان تمام چیزوں کا بوریا بستر اٹھادیا جائے جو کسی بھی طرح استعماریت کی یاد دلاتی ہوں۔ کاش آزادی اتنی سہل ہوتی جس طرح ایک زبان کی ساخت میں جذب ہونے والے کسی دوسری زبان کے اثرات کو یک قلم نکالا نہیں جاسکتا، اسی طرح لاشعور ( جوبہ قول ’لاکاں‘ زبان ہی کی ساخت رکھتا ہے) سے غیر کے کلامیوں کی دیس نکالا دینا آسان نہیں۔ (اس امر کی ایک اہم مثال انگریزی زبان ہے، ایشیا و افریقہ کے اکثرنوآبادیاتی ملکوں کے ادیبوں نے آزادی کے بعد بھی اپنی ثقافتی شناخت کی بازیافت اسی زبان کے ذریعے کی) تاہم لاشعور کی علامتوں کو تبدیلی و تکثیف کے عمل سے گزارا جاسکتا ہے اس لیے نوآبادیاتی لاشعور کی یورپی ڈسکورس سے آزادی، ان ثقافتی علامتوں کی دریافت نو ہے جنہیں فراموش کردیا گیا تھا۔‘‘(ص:۲۷۱)
ناصرعباس نیر سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا فراموش شدہ ثقافتی علامتوں کی دریافت نو کو ماضی کی طرف مراجعت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ درپیش یہ ہے کہ دریافت نو کا Frame workکیا ہوگا؟ کیا وہ فریم ورک جو آپ نے مستشرقین سے اخذ کیا ہے؟ کون سی ثقافتی علامت؟ کیا وہ ثقافتی علامتیں جس پر مغرب آپ کی زبان سے مہر تصدیق ثبت کرے؟ ان شقوں کے علاوہ اگر کوئی راستہ بچتا ہے تو وہ وہی جادہ اعتدال ہے ، جسے سرسید، حالی، شبلی، محمدحسین آزاد نے طے کیا ہے۔
میراموقف ہے کہ علم ایک اکائی ہے۔ نوع انسانی کا ورثہ ہے اسے مشرق و مغرب میں تقسیم کرنا مناسب نہیں۔ ناصر صاحب مشرق ومغرب کے درمیان، انگریز اور ہندوستانیوں کے درمیان اور حاکم و محکوم کے درمیان علمی اخذ و قبول کا مطالعہ طاقت کی حرکیات کے تناظر میں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ نہایت واضح ہے کہ محکوم کی ثقافت اور اس کا علم حاکم قوم کا عکس محسو س ہوگا۔مگرایسالگتا ہے کہ یہ نقطہ نظر کسی درست نتیجہ تک ہماری رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔
ناصرعباس نیر کے خیالات سے اتفاق کیا جائے یا اختلاف یہ الگ بحث ہے لیکن ان کی یہ کتاب غیرروایتی اور فکرانگیز ہے۔ اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتی کہ وہ خاصے ذہین اور منضبط فکرکے مالک نقاد ہیں۔ اپنے موقف کی توثیق کے لیے دلائل کی پیشکش کا طریقہ کار کیا ہوگا، دلائل کس طرح پرقوت ہوتے ہیں دلائل کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان تمام ہنرمندیوں سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ متن سے معنی کیسے کشید کیے جاتے ہیں، اصول کس طرح قائم کیے جاتے ہیں، استقرائی یا استخراجی طریقۂ کار سے کس طرح کے فائدے حاصل کیے جاسکتے ہیں، ناصر کا تنقیدی متن اس سلسلہ میں اردو تنقید کے سامنے ایک معیار پیش کرتا ہے۔ مابعدجدید تنقید کا بنیادی مدعا یہ ہے کہ کلیشوں سے احتراز کیا جائے، مسلمہ عقائد پر سوالیہ نشان قائم کیا جائے لیکن استثنائی صورتوں کے علاوہ اردو تنقید کے منظرنامہ میں یہ باتیں برائے نام ہی ملتی ہیں۔ شعورعامہ پر مبنی فکر ہی کی روشنی میں اب تک اردو ادب کا مطالعہ عام ہے اور اسی نہج پر دلائل جمع کرلینے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ناصرعباس نیر کا تنقیدی ذہن کبھی شعور عامہ کی لیک پر غور کرنے کا عادی نہیں ہے۔ مابعدجدید تنقید کی کماحقہ ادائیگی کے لیے جس نوع کے بین العلومی مطالعہ، اخاذ ذہن، ژرف نگاہی اور تیشہ نظری کی ضرورت ہے اس پر ناصرعباس نیر سوفیصد کھرے اترتے ہیں۔
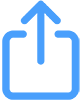 then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'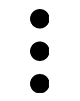 then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'








کوئی تبصرہ نہیں