آصف فرخی
نقاد بطور دشمن
’’وہ ایک کھوکھلے درخت میں تھا اور بستی والے آرے لیے آتے تھے۔‘‘
کہانی عجیب موڑ پر آگئی ہے۔ یہ کرائسس کا لمحہ ہے۔ امید و بیم کے دوراہے پر ایک خیال وحشت اثر سے مغلوب، حیران کھڑے سوچ رہے ہیں کہ آنے والا لمحہ چشمِ تماشا کو کیا دکھائے گا؟ کیا ان آنکھوں کے دیکھنے کے لیے معجزہ سامنے آئے گا کہ درخت میں چھپنے والے کو ظاہر نہ ہونے دے گا، قتل کی نیت سے آنے والے بے نیل مرام لوٹ جائیں گے، یا پھر بستی والوں کے آرے، تنے کو چیر کر اس کا راز افشا کردیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی کو خون میں نہلا کر اس کی بوٹی بوٹی الگ کردی جائے گی۔ اس خونی انجام کے خیال ہی سے جھرجھری آجاتی ہے۔ مگر یہ سب کچھ کہانی کی اپنی منطق سے بعید نہیں۔ ہم نہ تو کہانی کو اس ممکنہ انجام تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں، نہ آمادہ فساد بستی والوں کو باور کراسکتے ہیں کہ آرے واپس لے جائیں، ایک معصوم کا خون بہانے سے دریغ کریں۔ بستی والے بھی اپنے اختلاف کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں… آرے ان کی دلیلیں اور چھپنے والا بھی اپنی داستان کو پورا کررہا ہے۔ کھوکھلے درخت میں سمائے نہ سمانا، بنانے والے کے بجائے مخلوقات سے پناہ مانگنا اور پناہ نہ پانا، چھپنا اور اوجھل نہ ہوسکنا، آشکار ہوجانا اور آخر آرے چلانے والے کے ہاتھوں کی زد میں آکر میں لخت لخت ہوجانا… یہ اس چھپنے والے پربستی کے لوگوں کی ’’عملی تنقید‘‘ ہے۔ اتنی مائل بہ تشدد اور ہٹ دھرم کہ اب اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آرے چلانے والے ہاتھ پہچانے جاتے ہیں۔ وہ جس کی پگڑی کا سرا تنے کے باہر رہ گیا اور بستی والوں کو سراغ دے گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں، اس کی کہانی کیا ہے؟ بستی والے بھی اپنے عمل سے پہچانے گئے کہ نقاد ہیں۔ نقد ادب کام ہے، تنقیدی عمل کے واسطے آئے ہیں۔ ان کے خون آشام دندانِ آز کو نیا آذوقہ مل گیا۔ تنقید کے ارتقا میں ایک منزل طے ہوگئی۔ ادھر کچھ عرصے سے تنقید اور تخلیق کے باہمی تعلق پرجو بحث ہورہی ہے، اس میں خاص طور پر افسانوی ادب کے حوالے سے خوب گرمی آئی ہے کہ افسانے پر ان دنوں نقادوں کی نظر کرم ہے تو یہ اس اجڑی پجڑی صنف کے حق میں نیک فال ہے اور اس بات کا شگون کہ اب تو اس کے پو بارے ہیں، کسی نقاد نے افسانے پر مضمون لکھ دیا تو سمجھو سر پر ہما بیٹھ گیا، تاج و تخت، خزانے او رسکے کی امید بندھ گئی،یعنی جلد ہی گھورے کے دن پھر جائیں گے۔ یہ ساری بحث جس نہج پر چل رہی ہے اس پر مجھے رہ رہ کر خالدہ حسین کے افسانے کا وہ انجام یاد آتا ہے جو میں نے اوپر درج کیا ہے۔ کہانی یہاں ٹھٹھک کر رک جاتی ہے مگر وہ کرائسس جو اس فقرے میں سمٹ آیا ہے، چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، کتنے ہی سوال جوابوں کے منتظر ہیں۔ درخت آخر کب تک پناہ دے گا۔ ایک نہ ایک دن دشمنوں کو سراغ مل ہی جائے گا، پھر باہرنکلنے کا راستہ نہیں ملے گا اور نقاد کی تیغ تیز گردن پر تلی ہوگی۔ اردو افسانے پر اب کی بار افتاد نہیں، پیمبری وقت پڑا ہے۔
شاید یہ وقت پڑنا ہی تھا۔ افسانے کی نمو کی منطق کی طرح ناگزیر تھا۔ خرابی کی یہ صورت افسانے کی تعمیر میں ہی مضمر تھی۔ افسانے اور زندگی کے درمیان ایک لک چھپ لک چھپ کھیل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ چور پکڑا نہ جائے۔ کوئی چھپے کوئی ڈھونڈے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں چھپے اور وہاں پکڑے گئے، زندگی سے چھپنے والے، افسانے میں پکڑے جائیں اور وہ بھی کسی نقاد کے ہاتھوں، جو پھر آرے چلا کر ہی دم لے گا۔ اپنے آپ کو ایسے نقادوں سے بچانے کے لیے انتظار حسین نے ’اپنے کرداروں کے بارے میں‘ جو تحریر لکھی ہے (اختتامیہ، ’آخری آدمی‘) اس میں اعلان کیا ہے کہ ’’میں اپنے آپ کو زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ افسانے میں نہیں۔‘‘ انھوں نے اپنے واسطے اتنا تو تلاش کرلیا ہے مگر پگڑی کا سرا نہیں سمیٹ سکے۔ وہ خود ہی بتائے دیتے ہیں کہ کہاں چھپے ہیں اور کہاں سے پکڑے جاسکتے ہیں:
’’پیغمبروں اور لکھنے والوں کا ایک معاملہ سدا سے مشترک چلا آتا ہے۔ پیغمبروں کا اپنی امت سے اور لکھنے والوں کا اپنے قارئین سے رشتہ دوستی کا بھی ہوتا ہے اور دشمنی کا بھی۔ وہ ان کے درمیان رہنا بھی چاہتے ہیں اور ان کی دشمن نظروں سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ میرے قارئین میرے دشمن ہیں۔ میں ان کی آنکھوں دانتوں پرچڑھنا نہیں چاہتا۔ سو جب افسانہ لکھنے بیٹھتا ہوں تو اپنی ذات کے شہر سے ہجرت کرنے کی سوچتا ہوں۔ افسانہ لکھنا میرے لیے اپنی ذات سے ہجرت کا عمل ہے۔ مگر ہجرت ہمیشہ سے جان جوکھوں کا کھیل چلا آتا ہے۔ حضرت زکریاؑ درخت کے تنے میں جاکر چھپے تھے۔ مگر ان کی پگڑی کا سرا باہر نکلا رہ گیا۔ اس سے دشمنوں نے ان کا پتا پایا اور اپنے درخت اور اپنے پیغمبر دونوں کو دونیم کردیا۔ بہت لکھنے والوں نے اس طرح اپنی تحریر میں چھپنے کی کوشش کی ہے اور اپنے دشمن قارئین کے ہاتھوں پکڑے گئے۔‘‘
گویا پیمبری وقت اب افسانہ نگاروں کی اپنی صورت حال سے مترشح ہورہا ہے۔ بیان پیغمبروں کا سا اور ہاتھ میں معجزہ کوئی نہیں۔ یدبیضا تو بجھ گیا، دس احکام والی مٹی کی تختی رہ گئی۔ انتظار حسین کو تو اس کام کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، ورنہ چھوٹے موٹے افسانہ نگار اپنے معجزوں کے اعلان کے لیے نقاد ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس کے بعد بھی کسی کو قائل کرنے کی ضرورت پڑے تو پیمبری وقت کی بہتیری نشانیاں معاصر نقادوں کے ان ذخیرے ہائے مضامین تازہ میں بکھری پڑی ہیں جو انھوں نے بصد کرّ وفر افسانے کے احوال پر رقم فرمائے ہیں۔ جدید افسانہ نگاروں کا المیہ ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں نقاد میسر نہ آئے۔ اوریہ جو اس کمی کا مداوا کرنے کے لیے بعض نقادوں نے ادھر بھی توجہ دینی شروع کردی ہے تو تمام افسانہ نگاروں کو دن رات اظہار تشکر کے لیے ماتھا ٹیکنا اور دوگانہ حمد و ثنا ادا کرنا چاہیے، مبادا کوئی پوچھ بیٹھے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائو گے۔ ہم جھٹلانے والوں میں نہیں، تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔اس لیے کوئی چھوٹا موٹا، کانا کتھرا، آدھا پونا نقاد بھی افسانے کو مل جاتا ہے تو فی الفور سجدۂ شکر میں گر جاتے ہیں۔ اور تو اور، افسانہ نگاروں کے سرخیل جناب انتظار حسین، اقتدار میں افسانہ نگاروں کی پوری امت لیے، اسی عمل میں مصروف نظر آتے ہیں جب وہ شہزاد منظر صاحب کی کتاب کے فلیپ پر علی الاعلان شکر بجالاتے ہیں کہ فکشن کو آدھا پونا نقاد مل گیا لیکن ایسے سجدے کبھی کبھی بھٹکے ہوئے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جب ہم تنقیدی شعور جیسے مظہر کو نئی اختراع سمجھ لیں جب کہ وہ مدت مدید سے افسانے کے ساتھ چلتا آیا ہے۔ وقار عظیم نے ’’بوستان خیال‘‘ کی تقریظ میں غالب کے بعض جملے دہرائے ہیں۔ جناب مظفر علی سید نے اردو میں افسانوی ادب کی تنقید کے لیے زیادہ مستحکم بنیاد فراہم کرتے ہوئے غالب کے اعلیٰ چند فقروں میں سے ایک کو نقطہ آغاز قرار دیا ہے۔ اس روایت کے واضح نقوش انھیں رجب علی بیگ سرور کے یہاں بھی نظر آتے ہیں اور انھوں نے حالی اور شبلی کی تحریروں میں ایسی باتوں کی نشان دہی کی ہے جو فکشن کی تنقید کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔
جناب شہزاد منظر نے جن کے افسانے کی طرف متوجہ ہونے پر ہم انتظار حسین کی ممنونیت دیکھ چکے ہیں، اس بنیاد کے وجود ہی سے انکار کردیا ہے اور انتظار حسین ہی کا فقرہ دہرا کر اسے ’رعایتی نمبر دے کر پاس کرنے‘ کے مترادف قرار دیا ہے (’ذہن جدید‘ جون اگست 1991 ) لیجیے صاحب، موئے کو ماریں شاہ مدار، موصوف کا اگلا فقرہ تو آب زر سے لکھ کر رکھنے کے لائق ہے: ’’اردو میں شاعری کی حد سے زیادہ مقبولیت معاشرے کی پس ماندگی کاثبوت ہے۔ ‘‘ شاید اسی لیے نوبت آگئی ہے کہ غالب کو بھی پاس ہونے کے لیے کسی نقاد کے دلوائے ہوئے رعایتی نمبروں کی ضرورت پڑرہی ہے۔ غالب کو اردو افسانوی ادب کی تنقید کا نقطہ آغاز سمجھنے کے لیے میرے خیال میں غالب کا یہ شعر کافی ثبوت ہے کہ افسانے کی تنقید کا آغاز یہیں سے ہورہا ہے:
کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے عدو
کس دن ہمارے سر پر نہ آرے چلا کیے
پہلے مصرعے کے ’عدو‘ کو نقاد سمجھیں یا روایتی رقیبِ رو سیاہ، شعر کی کیفیت نقادوں کے ہاتھوں زچ ہوکر رہ جانے والے افسانہ نگار کی ہے۔ غالب سے لے کر انتظار حسین اور خالدہ حسین تک، اردو میں افسانوی تنقید کی روایت اسی آرے اور کھوکھلے درخت کے تسلسل کی کہانی ہے۔ اس پیمبری وقت میں تنقید اور تخلیق کے تعلق کی یہی ایک صورت بنتی ہے۔ پناہ دینے والے درخت بھی کم پڑتے جارہے ہیں اور نقادوں کو آرے چلانے کا شوق بھی بڑھتا جارہا ہے۔ سلسلۂ نقد ادب سلامت، ایک قتیل اور سہی۔ سر کٹا تو کیا کہ پہلے سرگراں تھے اب سبک سر ہوئے۔ تہہ تیغ ہوئے تو کیا، جان و دل اور لے آئیں گے بازار سے۔ اگر میسر نہ ہوئے تب بھی کوئی بات نہیں ان کے بغیر بھی کون سے کام بند ہیں۔ آج کل زیادہ تر افسانے ان تکلفات کے بغیر ہی لکھے جارہے ہیں۔ اب افسانہ نگاروں کو کون سمجھائے اور سمجھانے سے حاصل بھی کیا ہے کہ ’’آپ شہتیر نہیں ہیں کہ چرے جاتے ہیں۔‘‘ غزل کے روایتی عشاق کی طرح افسانہ نگار بھی حریص لذت آزار ہوئے جاتے ہیں کہ کوئی نقاد انہیں درخت کے کھکھل سے کھینچ کر باہر لائے اور مشقِ ستم کرے۔ ’’ہم کو ستم عزیز، ستم گر کو ہم عزیز۔ ‘‘ لیجئے، تنقید اور تخلیق کا رشتہ متعین ہوگیا۔ افسانہ نگار بھی خوش کہ ہم پر لکھا جارہا ہے اور نقاد بھی راضی کہ افسانوی ادب پرتنقید ہونے لگی ہے، جو ترقی کی نشانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں وار د ہونے والا تنقیدی مقالہ اس لائق بھی نہیں ہوتا کہ مقتول کا خون بہا فراہم کردے۔ افسانے سے معاصر تنقید کی دلچسپی مسلم، آپ اسے افسانے کی خوش نصیبی سمجھئے، افسانوی ادب کی تنقید کا عہد زریں قرار دیجیے، مجھے تو اس میں سے خونِ بے جزا کی بو آتی ہے۔
’میرا قاری میرا دشمن ہے‘ انتظار حسین نے یہ بات محض exposure کے خوف سے نہیں بلکہ اپنی سالمیت کے دفاع میں کہی تھی۔ اگر قاری کے بجائے مائل بہ تشدد، تیغ بہ دست نقاد سامنے آئے تو یہ خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب نقاد نے دشمنی پر کمر باندھی ہے۔ قاری تو بے چارہ اس کے مقابلے میں بے ضرر ہے، نقاد کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ اس کی دشمنی میں اتنا زہر ہے۔ ’نقاد بطور دشمن‘ اس فقرے کا ماخذ ہنری جیمز کی بعض تحریریں ہیں اور اس سیاق و سباق کی بازیافت مفید ہوگی کہ جن سے یہ فقرہ قائم ہے۔ ہنری جیمز کی ایک پسندیدہ تھیم یہ ہے کہ فن کار جو صناع اور خالق (maker) ہے، اپنا سربرستہ راز ہے، اپنے وجود کا دھڑکتا ہو امرکزہ، اپنی تخلیقات کے نقش و نگار میں بن دیتا ہے، جب کہ نقاد مکروہات دنیا کا وہ vulgar روپ ہے جو پھولوں کے اندر چھپے رس کو پی لینے والے لو بھی بھونرے کی طرح اس راز کو حاصل کرلینا چاہتا ہے، اپنی اس دیدہ دلیری کی بنا پر نقاد دشمن ہے۔ فن کار کا اپنے آپے کو بچائے رکھنے پر اصرار اور احتیاط اور نقاد کی گستاخی وپیش دستی… یہ باہمی کشاکش درخت کے تنے اور چھپنے والے پیغمبر کے اس استعارے سے منسلک ہے جس میں انتظار حسین کو فن کار اور نقاد کا تضاد نظر آیا تھا۔ انتظار حسین اور خالدہ حسین کے ہاں استعمال ہونے والے استعاراتی پیکر کو جاننے اور اس کی گیرائی کا اندازہ کرنے کے لیے ہنری جیمز کی افسانوی اور تنقیدی تحریروں میں اس استعارے کے مشتقات کو الٹ پلٹ کر دیکھنا بے سود نہ ہوگا۔
فن کار کے لیے نقاد کی دشمنی کا تصور، یقینا ایک تنقیدی concept ہے لیکن مجھے اس تصور کا بلیغ ترین اظہار جیمز کے افسانوی ادب میں نظر آتا ہے۔ اپنے طویل اور بے حد پر ثروت ادبی کیریئر میں کئی مرتبہ جیمز نے فن کاروں کو اور ان کی فن کارانہ زندگی کے گوناگوں تجربات کو موضوع بنا کر افسانے لکھے۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ جیمز کے نزدیک، تخلیقی تجربہ انسان کے جمالیاتی احساس کی متحرک اورفعال شکل ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، اگر تنقید فن کی پراسرار قوت کی تفہیم و تعبیر اور فن میں پنہاں زندگی کی معنویت کی باز یافت کا نام ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جیمز کے ان افسانوں سے بڑھ کر بلیغ، لطیف اور حساس تنقید شاید ہی کہیں اور ملے۔ اپنے ان افسانوں کی وجہ سے جیمز کو نقاد وں کا سرخیل ماننے میں مجھے کوئی تامل نہیں۔ جس طرح prefect فن کاروں کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح میرے لیے جیمز prefect ہے، شاید ضرورت سے زیادہ پرفیکٹ۔ ہنری جیمز کا امتیاز محض اتنا نہیں ہے کہ اس نے عملی طور پر یہ دکھایا کہ تنقید اور تخلیق کس طرح ایک ہی ذہن سے پھوٹ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو مستحکم وزرخیز بناسکتے ہیں بلکہ جیمز کا اصل کارنامہ یہ ہے… جس کی نظیر بڑی مشکل سے ملے گی… اس نے تنقید کو مجرد خیالات اور تصورات سے آزاد کردیا اور تنقید کو اس ٹیم ٹماق کے بغیر کامیاب و کامران دکھایا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے لکھا تھا کہ ہنری جیمز کی حساسیت اس قدر نفیس تھی کہ کوئی مجرد تصور (Ideal) اس کو غارت نہیں کرسکتا تھا۔ اردو افسانے میں ہم سیاسی زجر وتوبیخ اور ترقی پسندی کے زیر اثر مقبول ہونے والے جامد ’سیاسی شعور‘ کے اس قدر عادی ہوگئے ہیں… حالاں کہ ترقی پسندوں کا مطالبہ شعور کے بجائے محض ایک تصور سے وفاداری ہے… کہ ایسے ذہن کو شاید سراہ بھی نہ سکیں۔ جیمز کے ہاں، ’عظیم خیالات‘ کی کمی کے الزام کا جواب دیتے ہوئے ٹوڈو روف نے اپنی بے مثل کتاب، ’شعریات نثر‘ (Poetics of Prose) میں لکھا ہے کہ یہ بات اس طرح سے کہی جاتی ہے گویا فن پارے کی پہلی نشانی یہ نہ ہو کہ ’تکنیک‘ اور ’تصورات‘ کے درمیان تفریق کو ناممکن بنادے۔ ٹوڈوروف کا یہ جملہ ’’تکنیک کے تنوع‘ جیسے مطالعوں سے بہت آگے کی بات ہے، مگر یہ insight بھی جیمز کی مرہون منت ہے کہ اس کے تصورات پر گفتگو اس کی فنی ہیئت کے جائزے کے بغیر ناممکن ہے۔ افسانہ نگار کے لیے محض تصورات، ادھورے ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی ہوسکتے ہیں، جیسا کہ جلاوطن چیک ناول نگار میلان کنڈیرا کی کتابوں سے ظاہر ہے… حکومت کے نافذ کردہ تصورات کے جبر کے خلاف افراد کی کوشش اس کی ساری کتابوں کا محور ہے۔ اپنے مضمون ’تریسٹھ الفاظ‘ میں کنڈیرا ideal کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے:
’’مجھے کراہیت ان کے نام سے جو ایک فن پارے کو کم کرتے کرتے محض اس کے تصورات تک محدود کردیتے ہیں۔ مجھے گھن اور تنفر کہ جس چیز کو تصورات پر بحث کہتے ہیں، اس میں گھسیٹ لیا جائے۔ میری مایوسی اس عہد سے جو تصورات سے دھندلا گیا ہے اور فن پاروں سے بیگانہ ہے۔‘‘
ہم نے اردو نقادوں کو اسی نفرت کا موجب بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ آخر کو نقاد بھی تو مطلق العنان آمر ہیں، تنقید کے اسی جبر کے خلاف فن کار کی کش مکش، اسی دشمنی کا ایک روپ۔
تنقید اور فن کے باہمی رشتے کے بارے میں جیمز کے جو بھی خیالات رہے ہوں گے، ان خیالات سے» «The Figure in The Carpetـ نامی طویل افسانہ عبارت ہے (یہ جیمز کی درمیانی عمر کا لکھا ہوا افسانہ ہے، جب وہ تھیٹر میں شہرت عام حاصل کرنے میں ناکام ہوچکا اور نتیجتاً یہ طے کرچکا تھا کہ ’’یہ کوڑے کچرے کی فتح مندی‘‘ کا دور ہے اور اس میں فن کار کا مقدر عوام الناس کی ناقدری اور تنہائی ہے)۔ جیمز کے افسانے میں ایک نوجوان اور اوالوالعزم نقاد نے اپنے پسندیدہ مصنف ہیوویر یکر کے بارے میں ایک مقالہ لکھا ہے اور پھر جلد ہی اسے اس مصنف سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ مصنف اس مقابلے کے بارے میں اپنے تاثرات فوراً ظاہر کردیتا ہے کہ بات یہ نہیں کہ اس مقالے میں دقت نظر کی کمی ہے بلکہ یہ اس کی تصانیف کے ’اندرونی راز‘ کو اجاگر کرنے میں ناکام رہتا ہے حالانکہ ان تمام تحریروں کی معنویت اور ان کی تخلیق کا جذبۂ متحرک بھی یہی راز تھا۔
’’اپنے تمام تر ناطق تقلید اعتماد کے باوجود تم نے وہ ننھا سا نکتہ نظر انداز کردیا ہے۔ ‘‘ ویریکر اپنے نوجوان مداح اور ناقد کو افسانے کے اس منظر میں بتارہا ہے جو تنقید اور افسانوی تخلیق کے بارے میں لکھی جانے والی نازک اور حساس ترین تحریر ہے۔ ناقد (جو کہانی بیان کررہا ہے) یہ سمجھ رہا ہے کہ بوڑھے مصنف نے اس کے خیالات پڑھ لیے ہیں اور اس کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ دونوں میں کسی دن بحالی اور شفاعت ہوجائے گی۔ بوڑھا افسانہ نگار اپنی بات کو واضح کرتا ہے:
’’اس ننھے سے نکتے سے میری مراد ہے… کیا کہوں اسے؟… وہ مخصوص چیز جس کی خاطر میں نے اپنی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ کیا ہر ادیب کے لیے اس قسم کی ایک مخصوص چیز نہیں ہوتی، وہ چیز جس کی خاطر وہ سب سے زیادہ کاوش کرتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کے بغیر وہ لکھے گا ہی نہیں، اس کے جذبات کی شدت کا شدید ترین جزو، اس کے کاروبار کا وہ حصہ جس میں اس کے لیے فن کا شعلہ پوری شدت کے ساتھ بھڑکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے!‘‘
نقاد کچھ ششدر سا ہے اور احترام کے ساتھ ایک فاصلے پر پیچھے چلنے کی کوشش کررہا ہے… دیکھنے کی چیز ہے کہ ہر فقرہ کس طرح تصورات کو سمیٹے ہوئے کہانی کے عمل کو فروغ دے رہا ہے کہ کہانی کے لذت انگیز تنائو اور مجرد تصور کو علاحدہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ جیمز کا کمال فن ہے۔ یہ ننھا سا نکتہ واضح ہوتے ہوئے کہانی میں مضمر ہے۔ مگر ویریکر اپنے حوالے سے بات کرتا ہے۔
’’میں اپنی بات کرسکتا ہوں، میری تحریروں میں ایک تصور ہے جس کے بغیر میں اس سارے کام کی رتی برابر بھی پرواہ نہ کرتا۔ یہ اس پورے ڈھیر کا اعلیٰ ترین، مکمل ترین منشا ہے اور اس کا اطلاق میرے خیال میں صبر اور ہنرمندی کی فتح ہے۔ ‘‘ اور پھر ایک عجیب جملہ آتا ہے جو بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیمز کے اپنے تلخ تجربے پرمبنی ہے… مگر کس قدر سچ ہے!’’یہ بات مجھے کسی اور کے کہنے کے لیے چھوڑ دینی چاہئے، مگر کوئی اور یہ کہتا نہیں، اسی موضوع پر تو ہم اس وقت بات کررہے ہیں اور تقریباً ایک صدی بعد ہم بھی یہی کررہے ہیں! مگر ویریکر اور آگے چل رہا ہے۔ ’’یہ میری چھوٹی سی ترکیب ایک کتاب سے دوسری کتاب تک پھیل رہی ہے اور اس کی بہ نسبت ہر چیز اس کی سطح پر کھیل رہی ہے۔ میری کتابوں کی ترتیب ہیئت اور texture شاید کسی دن محرم ہائے راز (initiated) کے لیے اس کی ایک مکمل نمائندگی پر مشتمل ہوں گے۔ یہ فن کار کی توقع ہے اور بڑے دو ٹوک تنقیدی الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ اس سے آگے کا فقرہ تو تنقید کا پورا منشور ہے، تنقید کے منصب کا مکمل ترین بیان اور بے حد نفاست کے ساتھ:’’اس لیے بالکل فطری بات ہے کہ نقاد کے دیکھنے کی چیز بھی یہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے… یہی تو وہ چیز ہے جو نقاد کو حاصل بھی کرنا چاہیے۔‘‘ کیا تنقید اس ’’چیز پر انگلی رکھ کر نشان دہی کرنے سے زیادہ کچھ اور کرسکتی ہے؟ اس چیز کے حصول میں کامیابی ہی نقاد کی کامیابی… فتح مند دشمنی… اور حساسیت کا معیار ہے۔ ناقد اور مصنف کی بلیغ reticence کے درمیان کش مکش جومکالموں سے ہویدا ہے، افسانے کے اس منظر کو آگے بڑھارہی ہے۔ مصنف نے جس چیز کو ایک معمولی ترکیب کہا تھا، وہ اعتراف کرلیتا ہے کہ اس نے دراصل از راہِ انکسار ایسا کہا تھا اور وہ دراصل exquiste scheme ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش ہی مصنف کی اپنی نظر میں اس کی کامیابی ہے۔ ایک وقفے کے بعد ناقد سوال کرتا ہے، ’’کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو نقاد کی تھوڑی سی مدد کرنی چاہیے(یہی مطالبہ کہیں زیادہ واشگاف الفاظ میں نظیر صدیقی صاحب نے کیا ہے کہ جدید ادیبوں کو اپنی تحریروں کی شرح بھی لکھنی چاہیے۔ یعنی اس لیے تاکہ نقاد کو سراغ مل سکے۔ ممکن ہے کہ کوئی اور تیس مار خاں نقاد یہ تمنا ظاہر کردے کہ تحریر کی بھی کیا ضرورت ہے، شرح ہی کافی ہے۔ یعنی غالب اپنے دیوان کے بجائے شرح غزلیات لکھتے تو بہتر تھا)۔ ویریکر کا جواب اب اور بھی زیادہ دوٹوک ہے۔
’’مدد کرنی چاہیے؟ اور میں نے اپنے قلم کی ہر جنبش سے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ میں نے اس کے خالی چہرے کے عین سامنے اپنا منشا چیخ چیخ کر بیان کیا ہے۔‘‘ ویریکر نے باقاعدہ طور پر اپنا ہاتھ ناقد کے کندھے پر رکھ دیا ہے۔ ناقد کہتا ہے کہ تم The Initiated کی بات کرتے ہو، اس لیے Initiation کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ ویریکر کا جواب تنقید کے منصب کی ایک اور جامع تعریف ہے…
What else in heaven›s name is criticism supposed to be?
ویریکر کے جواب میں اس منظر کا تنائو اپنے عروج پر ہے۔
یہ اس لیے کہ تم کو اس کی جھلک بھی دکھائی نہ دی۔ اگر تم ایک مرتبہ یہ دیکھ لیتے تو زیر گفتگو عنصر ہی وہ کچھ ہوتا جو تم دیکھتے۔ میرے لیے یہ اتنا ہی قرینِ لمس ہے جتنا آتش دان کا پتھر اور پھر اس کے علاوہ نقاد بس ایک سادہ آدمی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو پھر بھلا بتائیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے باغ میں کیا کررہا ہے؟ آپ خود جو کچھ بھی ہیں، سادہ آدمی نہیں ہیں اور آپ سب کا اسباب وجود یہی ہے کہ آپ نازک خیالی کے چھوٹے چھوٹے عفریت ہیں۔ اگر میرا معاملہ ایک راز ہے تو میری تمام کوشش کے باوجود راز ہے، حیرت انگیز واقعے نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ خود میں نے اسے راز رکھنے کی ذرہ برابر کوشش نہیں کی۔ اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو آغاز سے ہی مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ جو ہوا وہ یوں تھا کہ تھوڑا تھوڑا کرکے میں اس سے واقف ہوتا رہا اور اس دوران میں اپنا لکھنے کا کام کرتا رہا۔
جملوں کے اس مترنم بہائو میں نقاد سے ایک زیر لب شکوہ ہے اور زندگی بھر کے کام کو ایک تموج کے ساتھ سمیٹ لیاگیا ہے۔ نقاد کے لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ متاثر نہ ہو۔ اس کا ارادہ بندھ گیا ہے کہ اس راز کا سراغ لگا کر ہی دم لے گا۔ مگر اسی جملے کے ساتھ ہی وہ نہایت ہی بھونڈا سوال داغ دیتا ہے کہ کیا یہ ’چیز‘ کسی قسم کا باطنی (esoteric) پیغا م ہے؟
اس پر اس کا منھ بن گیا… اور اس نے ہاتھ آگے بڑھادیا کہ جیسے مجھے شب بخیر کہہ رہا ہو۔ ’’ارے عزیزِ من، اسے اس طرح کی سستی صحافیانہ زبان میں نہیں بیان کیاجاسکتا۔
ویریکر کا طعنہ اور سلام رخصت آج کی بیش تر تنقید پر صادق آتا ہے۔ جدید اردو افسانے پرجتنا کچھ لکھا گیا ہے، اس میں سے زیادہ تر تحریریں پڑھ کر یہی جملہ یاد آتا ہے… ویریکر کا مایوس ہوجانا، نقاد کو برخاست کردینا، پھر جاتے جاتے اداسی بھری سرزنش۔ جاتے جاتے نقاد کا ایک اور سراغ اور اشارے کی درخواست کرتا ہے، تو ویریکر پھر اپنے ’’راز‘‘ کی ناقابل فراموش تعریف بیان کرتا ہے۔
میری تمام lucid کوشش اسے (یعنی نقاد کو) سراغ دے رہی ہے… ہر صفحہ اور ہر سطر اور ہر حرف یہ چیز اس ٹھوس طریقے سے موجود ہے کہ جیسے پنجرے میں پرندہ، مچھلی پکڑنے کے کانٹے پر لگا ہوا چارہ، چوہے دان میں لگایا ہوا پنیر کا ٹکڑا۔ یہ ہر کتاب میں اس طرح اترا ہوا ہے جس طرح تمہارے پائوں ان جوتوں میں اترے ہوئے ہیں۔ یہ ہر سطر پر حکمراں ہے، ہر لفظ کو منتخب کرتی ہے، ایک ایک حرف پرنقطے لگاتی ہے اور اعراب لگاتی ہے۔
نقاد پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ ’چیز‘ ہیئت ہے یا احساس کی شکل۔ اس کے جواب میں بھی ہمیں اتنا بلیغ جملہ ملتا ہے کہ افسانے کی بوطیقا ایسے ہی جملوں سے تعمیر ہوسکتی ہے۔ ’’اس (ویریکر)نے کہا، اچھا تمہارے جسم میں دل ہے۔ کیا یہ ہیئت کا عنصر ہے یا احساس کا عنصر؟ میں جس چیز کے بارے میں کہتا ہوں کہ کسی نے میری تحریروں میں نہیں دیکھا، وہ زندگی کا عضو ہے۔‘‘
نقاد بے چارہ (یہ نہ بھولیے کہ وہ نوجوان تھا) یہ طے کرلیتا ہے کہ اس ’چیز‘ کی جستجو کا اپنے آپ کو پابند کرلے گا۔ وہ اپنے آپ کو اس جنون کا محکوم بنالیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس چیز کے بارے میں قیاس ہی کرسکتا ہے۔
یہ اوائلی منصوبے میں کوئی چیز تھی، جیسے ایرانی قالین میں نقش ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ مثال استعمال کی تو اس نے بہت سراہا۔ یہی تو وہ دھاگا ہے، اس نے کہا جس میں میرے موتی پروئے ہوئے ہیں۔
اس کے باوجود نقاد اس پر اسرار ’چیز‘ کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا۔ اس کے پاس یوں ہی اٹکل پچو خیال آرائیاں ہیں۔ محولہ بالا منظر میں جیمز نے کمال Irony کے ساتھ دونوں کو ایک ہی گفتگو کے دوران، دو تیرتے ہوئے جزیروں کی طرح ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ ملاقات اور مکالمے کے باوجود یہ فاصلہ جدید تنقید کی موجودہ کیفیت ہے۔ ویریکر اسے ’’دنیا کی دل کشش ترین چیز‘‘ بھی قرار دیتا ہے، اور اس کے بیان کے لیے کسی قلم بہ دست نقاد کی آرزو بھی کرتا ہے اور جاتے جاتے نقاد سے یہ بھی کہتا ہے کہ ’’رہنے دو! یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔‘‘ سب سے بڑھ کر تو وہ اردو افسانوی ادب کے نئے نقادوں سے یہ بات کہہ رہا ہے جو اس کے الوداع کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیتے۔ اردو افسانے کے ایک ناقابل فراموش الوداع میں بھی اسی طرح بابو گوپی ناتھ کی آنکھوں میں ’’دکھ بھری ملامت‘‘ تھی۔ کیوں کہ اسے محسوس ہوا تھا کہ افسانہ نگار نے (بے حد جرأت کے ساتھ مصنف نے اس افسانہ نگار کا نام اپنے نام پر سعادت حسن منٹو رکھا ہے اور اپنے گریباں میں منھ ڈالنے کی یہ خود انتقادانہ جرأت ہمارے کس افسانہ نگار میں ہے؟) اسے betray کیا ہے۔ تنقید اور تخلیق کا تعلق اب تنقید کے ہاتھوں فن کے betrayal کا تعلق ہے۔
منٹو کی طرح جیمز کے لیے یہ betrayal بڑا مرکزی نکتہ ہے اور بڑی حد تک ذاتی بھی۔ حالانکہ اس کی تاویلیں مختلف ہیں اور یہ افسانہ بھی کثرت تعبیر سے پریشان ہے۔ جیمز کے بارے میں لکھتے ہوئے لیون ایڈیل (Edel) نے ناولوں جیسی دلچسپ سوانح عمری میں اس احساس کو ڈراما نگاری میں ناکام ہوکر شہرت حاصل نہ کرسکنے اور ایچ جی ویلز جیسے دنیاوی طور پر کامیاب ادیبوں کی نکتہ چینی کا نشانہ بننے کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ رچرڈ ایل مین (Ellman) کے نزدیک یہ جیمز کے جنسی الجھنوں اور دبی ہوئی جمال پرستی کا نتیجہ ہے۔ فرینک کرموڈ کے خیال میں یہ جیمز پر رومانوی تحریک کا اثر ہے۔ تاویلوں کی کثرت اور نقادوں کی ناکامی۔ وجہ بہر حال کچھ بھی ہو، جیمز 1890 کی دہائی میں لکھے جانے والے متواتر کئی طویل افسانوں میں یہ دکھا رہا تھا کہ شقی القلب، نافہم اور استحصالی دنیا میں سنجیدہ اور حساس فن کار کی کیا گت بنتی ہے جب کہ جیمز کے نزدیک زندگی میں اہمیت ہے تو فن کی:
It is art that makes life, makes interest, makes importance, for our «consideration», and application of these things, and I know of no substitutes whatever for the force and beauty of its process.
اس جملے میں makes کی وسعت کس قدر قابل توجہ ہے۔ جیمز ناول کواعلیٰ ترین فن کے منصب پر دیکھتا تھا اور اسی لیے تنقیدی شعور کو اہمیت دیتا تھا… ناول کا فارم اس کے لیے دراصل زندگی کا مسئلہ تھا۔ ناول کے لیے فارم کو ضروری نہ سمجھنے والوں کے حوالے سے اس نے لکھا:
«There is life, and as waste is only life sacrifical and thereby prevented from «counting» I delight in a deep breathing economy and on organic form.»
اس جملے پر فرینک کرموڈ نے رداچڑھایا ہے کہ افسانے کے فن کو نظرانداز کرنا، زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ یہ الفاظ گو کہ جیمز کے نہیں ہیں، مگر اس کے خیالات کی بالکل صحیح ترجمانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ افسانے کی تنقید کا سب سے کڑا معیار ہے، شاید اس لیے کہ جدید اردو افسانے کی بیش تر تنقید اسی طرح زندگی کا ضیاع معلوم ہوتی ہے۔
نقاد بہ طور دشمن… یہ فقرہ بھی فرینک کرموڈ نے جیمز کے مفاہیم کی وضاحت کے حوالے سے لکھا ہے۔ فن اور دنیا کی کش مکش میں نقاد دنیا کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے دشمن ہے۔ اس دشمنی کا بہترین اظہار ’’دی فگر ان دی کارپٹ‘‘ میں ہوا ہے اور کرموڈ نے اپنے مضمون میں جیمز کی دوسری تحریروں سے اس افسانے کے مرکزی نکتے کی مماثلت تلاش کی ہے۔ جیمز کے اس افسانے نے بہتیرے نقادوں کو متوجہ کیا ہے اور ساختیاتی مطالعے کی ایک جنگ زرگری میں اس افسانے کے تجزیے کو اہم مقام حاصل ہے۔ ’’نقاد بہ طور میزبان‘‘ کا مصنف جے ہلسن ملراس جنگ میں زیادہ ہی پرجوش ہے، مگر اہم تر مضمون ولف گینگ ایزر (Iser) کا ہے جو اس افسانے کے حوالے سے بحث کرتا ہے کہ قاری یہ توقع کرتے ہیں کہ افسانے کی تفصیلات چھلکے کی طرح ہیں جس کے اندر معنویت کی گری ہوگی جب کہ معنویت کو ئی علاحدہ چیز نہیں ہے۔ جیمز نے اپنے دور اول کے تنقیدی مضمون ’’دی آرٹ آف فکشن‘‘ میں ناول نگار کے حوالے سے لکھا تھا:
«His maner is his secret, not necessarily a jealous one. He cannot disclose it as a general thing if he would, he would be at a loss to teach it to others.»
اس کے باوجود جیمز کو توقع تھی کہ ماہر قاری یعنی نقاد اس راز کو بھانپ لیں گے۔ چتونوں سے باطن کا سراغ لگاسکنے والے ناقد کی عدم موجودگی، جیمز کے لیے صدمے کا سبب تھی۔ اپنی نوٹ بک میں جیمز نے ابتدائی خیال سے لے کر تکمیل تک، ’’دی فگر ان دی کارپٹ‘‘ کا ذکر کیا ہے۔ ناول نگار کا انداز اس کا راز ہے، یہی احساس نقاد میں مفقود ہے اور جیمز ’’تجزیاتی تحسین کی کمی‘‘ کا برملا شکوہ کرتا ہے۔ ویریکر کے راز کی جستجو میں اپنے اس مقصد میں تنقید کی ناکامی کی تمثیل ہے کہ یہ نہیں معلوم کیا جاسکتا کہ فن کار کی کوششوں کا منشا کیا ہے۔ کرموڈ نے نوٹ بک کے اس اندراج کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں جیمز یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ’’شریک راز‘‘ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ:
’’وہ نہیں جانتے، انھوں نے محسوس نہیں کیا، نہ اندازہ لگایا اور نہ ادراک کیا… اس اندرونی خیال کا … یہ حسنِ خاص… جو جاری وساری ہے اسے قابو میں اور متحرک رکھتا ہے۔‘‘
اس حسن کی موجودگی سے باخبر ہوجانے کے باوجود نقاد اس سے واقف نہیں ہوسکتا اور مصنف سے ہی متنفر ہوجاتا ہے۔ نقاد کی تلاش کا محور ہی غلط ہے۔ وہ معنویت کو کسی مدفون خزانے کی طرح ڈھونڈرہا ہے، جب کہ وہ پراسرار چیز موضوع میں نہیں بلکہ خود موضوع کے برتائو میں، افسانہ نگار کے انداز میں پنہاں ہے۔ یہ ناواقفیت مہلک بھی ثابت ہوسکتی ہے۔ ’’دی ڈیتھ آف دی لائن‘‘ میں جیمز نے ایک معمر ادیب کا نقشہ کھینچا ہے جس کو بے پناہ شہرت ملتی ہے، بے تحاشا انٹرویو ہوتے ہیں اتنے زیادہ کہ مارے مداحی اور محبت کے یہ معاشرہ اسے ہلاک کرڈالتا ہے اور اس کے باوجود اسے سمجھنے اور اس کی تحریروں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی شہرت، تنقیدی تجزیے کی جگہ لے لیتی ہے اگر چہ اس کا نعم البدل نہیں بن سکتی اور یوں بھی فن کار کی تباہی کی صورت بنتی ہے۔ دشمنی کے کئی روپ ہیں اور اس کا دائرہ اب مکمل ہے۔
فرینک کرموڈ نے ’دی فگران کارپٹ‘ کے ایک ٹکڑے میں واضح جنسی تلازموں کی نشان دہی کی ہے۔ راز کے حصول کے لیے نقاد کی کوشش کے لیے ‹Penetration› کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ کرموڈ نے انتباہ کیا ہے کہ یہ افسانہ بے اثر تنقید کا خاکہ اڑاتا ہے، پیشہ ور نقادوں کی ناکامی کی تصویر ہے مگر میرے حساب سے اس افسانے میں کئی معنویتی جہتیں ہیں اور اس افسانے کا کئی طرح سے تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔ شلومتھ رمون کینن (Sholomith Rimmon Kenan) افسانے میں ابہام کی تشریح کرتے ہوئے ’’قالین کے نقش و نگار‘‘ میں معنویت ڈھونڈنے کی قارئین کی کوشش کو، افسانے کے باطن میں نقادوں کی تلاش کے متوازی قرار دیتی ہیں۔ جیمز کے بیانیے کی ایک اور بے حد اہم تفہیم Tzvetan Todorov کے ہاں ملتی ہے۔ ’’افسانے کی شعریات‘‘ میں جیمز پر دو مکمل مضامین ہیں، جن میں سے پہلا مضمون اس افسانے کی تشریح سے شروع ہوتا ہے: ’’جیمز ین بیانیہ ہمیشہ کسی مطلق اور غائب مقصد کی تلاش پر مبنی ہوتا ہے۔‘‘ ’’پینچ کا پھیر‘‘ اور دوسرے افسانوں سے گزر کر ٹوڈروف اس نتیجے پر پہنچتا ہے:
ہم اب جانتے ہیں کہ ہنری جیمز کا راز (اور بلاشبہ ویریکر کا راز بھی) ایک راز کی موجودگی میں واقع ہے، ایک غائب اور مطلق مقصد میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس راز کو آشکار کرنے اور غائب کو حاضر بنانے کی کوششوں میں۔
بیانیے کی لذتوں او رمعنویتی کثرت کے ایک نئے امکان کی نشان دہی ہے۔ تاہم افسانے کی ایک جہت یہ ہے کہ جس کی طرف کرموڈ نے اشارہ نہیں کیا اور جو اس وقت نمایاں تر معلوم ہوتی ہے جب انتظار حسین او رخالدہ حسین کے محولہ بالا بیانات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور ان میں موجود Correspondence (جیمز کا پسندیدہ لفظ) کا اجمالی جائزہ لیا جائے۔ انتظار حسین بقول خود نقادوں کی آنکھوں دانتوں پرنہیں چڑھنا چاہتے۔ ویریکر ایک ہم درد اور سمجھ دار نقاد کا خواہاں ہے اور شاید ایسے معجزے سے مایوس بھی۔ وہ درخت کے تنے میں کھڑا ہوا ہے۔ جیمز کا افسانہ آگے چل کر نقاد کی دست درازی کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ نقاد کے لیے اس راز کا حصول ایک خبط بن جاتا ہے (کیا نقاد اس کے ذریعے سے کنٹرول اور طاقت چاہتا ہے، یا تخلیق کاراز دریافت کرکے اسے مسخر کرنا چاہتا ہے، یا یہ حد سے بڑھا ہوا محض تجسس ہے؟) وہ ویریکر کی بیوہ سے شادی کرنے کا بھی ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس راز تک رسائی حاصل کرلے۔ اس کی ناکامی کو جیمز نے ہلکے ہاتھ سے اور خنداں زنی کرتے ہوئے لکھا ہے مگر ادیب کے وجود کا راز حاصل کرنے کے لیے نقاد کی اس بے قراری کا یہ بیان الم ناک بلکہ ڈرائونا معلوم ہوتا ہے۔ نقاد اس راز کے حصول کے لیے کسی بات سے دریغ نہیں کرے گا۔ چاہے فن کار کے قلب تک پہنچنے کے لیے اسے کھلونے کی طرح چکنا چور ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے اور افسانہ نگار کو پناہ دینے والا کھوکھلا تنا اس کی ضربوں کی زد میں ہے۔ نقاد کی دشمنی ہمیں یہاں تک لے آئی ہے اور شاید یہ لذت کش رسم آزار ہونے کی انتہا ہے کہ ہم پھر بھی نقادوں کے ممنون احسان بلکہ حلقہ بہ گوش ہوئے جاتے ہیں۔
بعض لوگ جن میں اکثریت افسانہ نگاروں کی ہے، ان نقادوں کو جدید اردو افسانے کا کچھ اس طرح سے نجات دہندہ سمجھتے ہیں کہ نقاد بس آکر جلوہ نما ہوا یا اس نے تبسم فرمایا اور افسانے کے پہاڑ سے مسائل کوہ طور والی ’جلتی جھاڑی‘کی طرح روشن ہوگئے۔ کسی کی نظر کرم سے یوں ادبی مسائل حل ہوا کرتے ہیں، نہ ان سوالات تک رسائی ہوتی ہے جن سے نبرد آزما ہوکر کسی مخصوص صنف کے ادبی سرمائے کی تفہیم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بہت سے مضامین کے ڈھیر لگ جانا، ان مسائل کو سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوا ہے۔ آپ مجھے ناشکرا کہیے یا احسان ناشناس، افسانوی ادب پر نقادوں کی اس یلغار سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ الٹا یہ ہوا ہے کہ افسانہ چیونٹوں بھرا کباب معلوم ہونے لگا ہے۔ نقادوں نے بھی حسب عادت خلعت بانٹنے اور مسندیں الاٹ کرنے سے زیادہ سروکار رکھا ہے، گویا شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار کا سرا حسنِ انتظام ان ہی کے دم قدم سے تو ہے اور اس تمام دھوم دھڑکے میں ان اصل سوالات کو بارہ پتھر باہر ہی رکھا، جن سے نبرد آزما ہوکر اردو افسانہ اور اس کی تنقید اپنے سفر کے اگلے مرحلے میں ایک نئے شعور اور خود آگہی کے ساتھ داخل ہوسکتے ہیں۔ میرے اپنے کچے پکے حساب سے ان سوالات کا محیط جس طرح سے بنتا ہے اس کی بھی نشان دہی لازم ہے۔ واقعیت سے علامت تک، اردو افسانہ جن مراحل سے گزرا ہے، موضوعات کے اعتبار سے بھی اور ہیئت کے حساب سے بھی، تو کیا ان مراحل کے نقطہ ہائے اتصال کو روایت کا نام دیا جاسکتا ہے اور کیا یہ مفروضہ روایت ایک ایسا بنیادی discourse فراہم کرتی ہے کہ جس کی مسلمہ، مروجہ یا ممکنہ اشکال معنویت کی تلاش یا تخلیق میں ہماری مدد گار ہوسکتی ہیں؟ (اس امر کی تصدیق کہ ایسا ممکن بھی ہے اور مفید بھی، کسی نقاد کے بجائے مشتاق احمد یوسفی کی ’’آب گم‘‘ سے ہوتی ہے جو اپنے شیوۂ بیاں اور پیرایۂ اظہار کے سبب معاصر اردو ادب کی ممتاز کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کو افسانہ کہنا مشکل ہے اور شاید غیر ضروری بھی، مگر مصنف اردو افسانے کی ڈھلی ڈھلائی اور جانی پہچانی رسومات بیان کو Parodic intent کے ساتھ انگیخت کرسکتا ہے اور نفسِ مضمون کو ان کے سانچے میں ڈھال کر معنی کی ایک ایسی نئی جہت کی تخلیق کرسکتا ہے جو اپنی جگہ اہم تو ہے ہی، اردو کی افسانوی روایت کا ایک تخلیقی مطالعہ بھی ہے۔ مجھے ’’آبِ گم‘‘ میں بے پناہ تنقیدی شعور نظر آتا ہے اور اس کے سامنے بہت سے ثقہ نقادوں کی تحریریں لطیفوں کی کتابیں معلوم ہوتی ہیں)۔ روایت کے بنیادی سوال کے بعد متفرق افسانہ نگاروں کے اس سے تعلق کی بات آتی ہے مثلاً بیدی کو لیجیے جن کا نام پچھلے دنوں خاصے احترام سے لیا جانے لگا ہے۔ بیدی کے افسانوی artifacts اب تک بالعموم برتے جانے والے تنقیدی آلات (پلاٹ، کردار، مکالمہ وغیرہم) کے یک رخے استعمال سے گرفت میں نہیں آتے اور اپنے verisimilitude کی تعبیر کے لیے اپنے سمجھنے اور پرکھنے والوں سے معنویت کی تشریح کے لیے اپنی singificance کے بحرِ متلاطم میں اترنے اور ڈوب جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس میں ڈوبے بغیر ہم پار نہیں اتر سکتے۔ اس مطالبے کا محض سامنا ہی کرنے کے لیے جس حساس تر شعریات افسانہ کی ضرورت ہے ہم اس سے کوسوں دور ہیں مگر کہانی کا سفر جاری ہے۔ تتلیاں پکڑنے والا جال ہاتھ میں لے کر زندگی کے پیچھے بھاگنے والے افسانہ نگار پر اس سفر میں جو گزری ہے اس سے زندگی اور فن کی کیسی تصویریں بنتی ہیں؟ اس سفر کا تازہ ترین مرحلہ، نقادوں کے نزدیک علامت کے زوال اور افسانے میں کہانی کی واپسی سے عبارت ہے اور ہر دو نقادوں نے اپنے پسندیدہ افسانہ نگاروں کی اتنی پیٹھ ٹھونکی ہے اور داد و تحسین کے ڈونگر ے برسائے ہیں کہ بس اور اس کے باوجود گہرے اور گمبھیر سوال منھ چڑا رہے ہیں۔ افسانہ لکھنے والوں کی جس پیڑھی سے میں تعلق رکھتا ہوں اسے اپنے سے ایک نسل پہلے آنے والوں کے کام میں سے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین کے بعد ابھر کر آنے والی پیڑھی میں میرے حساب سے جو کلیدی افسانہ نگار ہیں… انور سجاد، خالدہ حسین، بلراج مین را، ضمیر الدین احمد، سریندر پرکاش، عبداللہ حسین، حسن منظر، مسعود اشعر، محمد سلیم الرحمن، بلراج کومل، غیاث احمد گدی، الیاس احمد گدی، اسد محمدخاں، احمد ہمیش، نیر مسعود اور منشایاد… ان کے افسانوی اسٹرکچرز کے تاروپود میں اتر کر ان کی معنیاتی جہتیں کیوں کر دریافت ہوسکتی ہیں؟ انھوں نے مروجہ افسانوی سانچوں کو کب اور کس طرح توڑا یا بحال رکھا، ان کے ہاں Process of signification کی باز یافت ہمیں اس معرفت کی طرف کیسے لے جاسکتی ہے کہ فن کس طور ’’زندگی کی تخلیق‘‘ کرتا ہے۔ ناخن کا یہ قرض ادا کیے بغیر کہانی کی واپسی کا جشن محض بغلیں بجانے تک محدود رہے گا۔ تقسیم کے وقت مغویہ عورتوں کی طرح جن میں بیدی کی لاجونتی بھی شامل تھی، خوشی کے مارے یہ اعلان کرتے پھر نا کافی نہیں ہے کہ ’کہانی واپس آگئی ہے‘ ہم پہلے کہانی کو دل میں بسانا تو سیکھ لیں۔ ان سب باتوں سے دور ہمارے نقاد جوش جستجو کے مارے ہوئے کھوکھلے تنے کی تلاش میں سارا جنگل کاٹے ڈال رہے ہیں۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناقد…
افسانوی ادب پر نقادوں کی توجہ مبذول ہوئی بھی ہے تو ایسے وقت میں جب خود افسانے میں مندی کا رجحان ہے۔ انور زاہدی کے منفرد اور اہم مجموعے پر لکھتے ہوئے خالدہ حسین نے اپنی بات ہی یوں شروع کی ہے: ’’موجودہ دور میں اردو افسانہ تصنع، بے روح تجریدیت اور تخلیقی تجربے کے جس تکدر سے گزررہا ہے… ‘‘ اور اس کے باوجود شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو جب کوئی نہ کوئی بلند مرتبت نقاد منبر پر کھڑے ہوکر ’’جدید افسانے کے سرمائے میں گراں قدر اضافے‘‘ کی نوید نہ سناتا ہو جو فلاں کے مجموعے کی اشاعت سے عمل میں آیا ہے اور شاید ہی کوئی افسانوی مجموعہ ایسا چھپتا ہو جسے درجہ اول کے لائق شاہ کار نہ قرار دیا جاتا ہو۔ (اگر ہر نئی کتاب شاہ کار ہے تو پھر ہم یہاں اس گڑھے میں گرے ہوئے کیا کررہے ہیں؟) دل خوش کن نوید ہائے مسرت کی تعداد بڑھتی جارہی ہے اور افسانہ ہے کہ پچھڑتا جارہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کا جدید افسانہ اپنے بل بوتے کے بجائے بچے جمورے کی طرح نقاد کی دہشت سے بول رہا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی سامنے نظر آرہا ہے:
معاملہ جب یہاں تک آپہنچے کہ ایک خود مختار کہلانے والا افسانہ نگار عدالتی ٹرم کے مطابق کسی نقاد کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کا بھی مختار کل مقرر کردے کہ وہی اس کے تخلیقی معاملات کو جس طرح چاہے dispose of کرتا پھرے تو مجھے اس میں تخلیقی قوتوں ہی کا زوال نظرآتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے تنقید کی ادبی پناہ یعنی Literary Asylum میں چلے جانے کے مترادف ہوگا۔
یہ اقتباس رام لعل کے مضمون ’’اردو ادب کی تنقید میں دہشت پسندی‘‘ سے لیا گیا ہے۔ رام لعل افسانوی ادب کی تنقید میں اس لیے اہم ہیں کہ انھوں نے پہلی بار، شمس الرحمٰن فاروقی کے مطابق، افسانے کے علاحدہ صنفی مطالبات کا اعادہ کیا۔ وہ افسانے کے تجزیاتی نقاد تو بہر حال نہیں ہیں، مگر سرد و گرم زمانہ چشیدہ افسانہ نگار ہونے کے ناتے افسانے پر ان کی تحریروں میں مجموعی فضا کے حوالے سے وہ Horse sense ہے، ایک سیدھا سچا اور درد مندانہ احساس جو بسااوقات میرے دل کو لگتا ہے۔ اسی لیے محولہ بالا مضمون کایہ بیان میرے لیے موجودہ صورت حال پرجامع تبصرہ ہے کہ ’’ہمارے افسانوی ادب میں اس وقت سب سے خطرناک چیز افسانے کی تنقید بن گئی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کا افسانوی ادب تخلیق ہی نہیں کیا گیا ہو یا اسی معیار کی تنقید نہ لکھی گئی ہو لیکن عام طور پر تنقید نے اس وقت جس قسم کی لٹریری دہشت پیدا کردی ہے، اس کے مضر اثرات نئے لکھنے والوں پر واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔‘‘
یہ اثرات اتنے واضح ہیں کہ اس بیان پر مزید تبصرے (یا تنقید) کی گنجائش نہیں۔ یوں بھی رام لعل اپنے اس تنقیدی بیان میں اتنے کھرے افسانہ نگار رہتے ہیں کہ استدلال کا تانا بانا تیار کرنے کے بجائے اپنی بات کو ماجرے کے ڈھنگ پر پیش کرتے ہیں۔ تجربے کی ایک مماثل کیفیت کا بیان انھوں نے ’’اردو افسانے کی تنقید میں دختر کشی کا جدید رجحان‘‘ میں کیا ہے جہاں وہ شاعری کے ساتھ ہونے والے ترجیحی سلوک کو کہانی کے حق میں دختر کشی قرار دیتے ہیں۔ ایک بار پھر تجربے کے نامیاتی رجحانات اپنی طرف متوجہ کرلیتے ہیں:
’’پتا نہیں کیوں اور کب افسانہ نگاری کرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھ گئی تھی کہ افسانہ پر تنقید بھی ضروری ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی نقاد میرے افسانوں پر قلم نہیں اٹھائے گا میں بڑا ادیب ثابت نہیں ہوگا…! یہ میری ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے آس پاس آنے والے سارے ہی ادیبوں کی بدقسمتی رہی ہے کہ ان پر تنقید کی ایک دہشت طاری کردی گئی ہے۔ ہمارے سامنے نقاد کا کردار ایک دوست اور رفیق سفر کا نہ ہوکر یاتو بالکل ایک جلاد کا سا بن گیا ہے، یا پھر ایک ایسے بااختیار اور بڑے افسر کا سا جس کی معمولی سی سفارش سے ہم ناجائز طور پر ترقی کی کئی منزلیں پار کرسکتے ہیں۔‘‘
گویا اب پانی سر سے اونچا ہوچکا ہے۔ فی الوقت اس بحث کی شاید ضرورت نہ ہو کہ اس خطرے کو دعوت دینے والے خود ادیب لوگ ہی تھے کہ جنھوں نے تنقید کو وہ جادو بنایا جو سر چڑھ کر بولے اور اب نقاد پریر تسمہ پا ہیں یا فرینکن اسٹائن جو فن کار کو اپنے اشاروں پر تگنی کا ناچ نچارہے ہیں۔ رام لعل نے بات ایک افسانہ نگاری کی انفرادی سطح سے شروع کی ہے اور نقاد کی دشمنی کا ہدف بھی یہیں پر ہے۔ رام لعل نے کئی مثالیں دی ہیں کہ ’’ان کی بعض کہانیوں کے لیے مختلف مفاہیم تجویز کیے گئے، یہی رائے زنی وہ دامِ صیاد ہے کہ جس میں بندھ جانے کے بعد تنقید دشمنی دکھاسکتی ہے۔ بہترین خواہشات کے باوجود، تنقید نقصان پہنچا سکتی ہے، ‘‘ چیک ناول نگار جوزف اشکور ویئسکی (Skvorecky) زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ فلم کے نقاد انتونن لیہم (Liehm) سے اپنی گفتگو کے دوران، جو اس کے مجموعۂ مضامین Talkin Moscow Blues میں شامل ہے، وہ ہیمنگوے کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہر فن کار کو اپنے اندر بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے اپنی خامیوں کا اتنا گہرا احساس ہوتا ہے جو اسے حد سے زیادہ اعصاب زدہ بنا کر رکھ دے۔ ہیمنگوے کے جیسے حساس اور اعصاب زدہ فن کار پر تنقید کا اثر اس قدر شدید ہوسکتا ہے کہ اسے فنکار کے طور پر غارت کرکے رکھ دے۔ میں مثال سے پوری طرح متفق نہیں، تاہم یہ واضح ہے کہ تنقید دہانِ زخم میں گندھک رکھنے سے غیر معمولی دل چسپی رکھتی ہے اوریہ کام وہ بہت نامحسوس طریقے پر بھی کرسکتی ہے۔ اشکور ویئسکی نے جن مشکلات کا ذکر کیا ہے افسانہ نگار ان سے نمٹنے کے عمل ہی میں پختہ ہوتا ہے اوراس پر عمل اس کی خودآگہی کا ہے۔ اگر کسی نقاد کی رائے اس پورے سلسلے میں شارٹ کٹ یا متبادل راستے بتانے لگے تو افسانہ نگار کی تخلیقی قوت کے ساتھ کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ اس طرح نقاد فن کار کی نشوونما اور تخلیقی اعتبار کو ختم کردیتا ہے اور اسے اپنی لاگ ڈانٹ کا محتاج بنادیتا ہے۔ ہماری تنقید نے ایسے کئی عددخر کار کیمپ کھول رکھے ہیں جن میں فن کار بیگار بھگت رہے ہیں… اپنی خوشی سے!
تنقید کا یہ سلوک manipulation سے بڑھ کر coercion تک پہنچ سکتا ہے۔ دشمنی کے اس روپ کی افسانہ نگار کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ افسانہ نگار کے لیے اسباب کچھ بھی ہوں یہ صورت حال تکلیف دہ ہے۔ چناں چہ رام لعل نے لکھا ہے کہ ’’یہ رویہ سماجی اور سیاسی برائیوں کی پیداوار بھی ہوسکتا ہے لیکن جب جب یہی رویہ ادب کی تنقید میں بھی داخل ہوجاتا ہے تو آ پ اندازہ کرسکتے ہیں کہ ادب کی سچی اور کھر ی تخلیق کرنے والے کس قسم کی افسردگی، بے دلی، بیزاری اور جمود کا شکار ہوسکتے ہیں۔ دشمنی کا زہر اب پوری طرح اپنا کام دکھا رہا ہے۔ نقادوں نے چلے میں جو تیر چڑھا رکھے ہیں وہ سب اسی زہر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کا نشانہ معلوم۔ رام لعل لکھتے ہیں کہ ’’آرٹ کی دنیا میں اگر اس (ادیب) کا سابقہ اپنے سماج کے اندر رہنے والے غیر مصنف سماج دشمن اور سیاسی بازی گروں سے کہیں زیادہ ادیب دشمن اور ادب کو بھی سیاسی اکھاڑا سمجھنے والے نقادوں سے بھی پڑے گا تو وہ بے چارہ اور کہاں جائے گا۔ لیکن میں اسے بھی ایک سماجی ناانصافی سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ ایسے نقادوں کو بھی اپنے افسانوں کے کردار ہی سمجھتا ہوں جو ہمارے ادبی معاشرے کی decadence کی ہی وجہ سے کبھی کبھی تو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اور کبھی کبھی literary coup کرکے ہی تنقید کا سارا نظم و نسق اپنے قبضے میں کرلیتے ہیں اور پھر بڑی معصومیت سے ہم افسانہ نگاروں پر اس طرح کے اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں…‘‘ یہ فیصلے ہم کس زور شور سے سن رہے ہیں، ان کی گھن گرج سے رن کانپ رہا ہے، چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ وہ ہندوستان ہو یا پاکستان، ادبی establishment کا سارا بوجھ ان کے پس پشت ہے اور یہ اپنے اقتدار کو perpatuate کرنے کے لیے نقاد کو بہ طور آلہ کار استعمال کررہے ہیں۔ ادبی سیاست اپنی تمام تر بازی گری کے لیے تنقید کی زبان استعمال کررہی ہے جو اسے ہمارے نقادوں نے سکھلائی ہے۔ ادبی خدائوں کے لیے سہولت ہی سہولت ہے، اپنی رضا کو تنقید کا چولا پہنا کر اس سے بڑے بڑے کام لے رہے ہیں۔ اس کو نیچا دکھا دیا، اس کے نمبر بڑھادیے، اندھے کی ریوڑیاں اسے بانٹ دیں، ایک کو بانس پر چڑھا دیا، ایک کو خاک میں ملادیا، کسی کی دستار گرادی، کہیں دھول دھپا، غرض کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آج معاشرے میں ادب کو زک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی تنقید ہے جو تنقید نہیں۔
اب تنقید طاقت (power) ہے اور طاقت کے پاس سارا اختیار۔ اس طاقت کے brokers ہمارے نقاد ہیں جو ہمہ وقت اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے کے درپے رہتے ہیں، negotiations میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی آشیرواد کے بغیر کوئی ادب کی دنیا میں پنپ نہیں سکتا۔ کسی نے داخل ہونے کی جرأت کرلی تو ان کے گر گے ٹھیک کردیں گے یا پھر اپنی بے کسی کی موت مرنے کے لے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، اگر نووارد ان کی پناہ میں آجائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرلے تو کسی فہرست میں جگہ پانے کی امید رکھ سکتا ہے۔ ان سے الگ تھلگ رہ کر اپنا موٹا جھوٹا کام کرنا چاہے تو آزادی اظہار کا اعادہ کرنے والے اجہل مدیر بھی ہیکٹری میں کسی سے کم نہیں۔ مہرے آگے بڑھانے میں ان کے کردار جو نہ مانے تو اس کی وہی سزا جو کالے چور کی۔
نقاد اب گویا nucleus ہے، اس سماجی گٹ بندی کا جو power clique کے طور پر کام کرتی ہے اور ادبی تنقید کہلاتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کی سماجی شکلیں واضح ہیں اور وہ نظریاتی جامے میں ملبوس نظر آتی ہیں مگر سیاسی روپ بالعموم نہیں بھرتیں۔ ورنہ ادیب کے victimization کی بھیانک شکل تو وہ ہے جب حکومت عملی تنقید کرتی ہے ! بیسویں صدی کا شاید ہی کوئی معاشرہ اس سے محفوظ رہا ہو۔ اس دبائو کی ہزار شکلیں ہیں اور ہزار روپ اور ان میں نقاد کتنی آسانی سے ملوث ہوجاتے ہیں جیسے کہ جلادی سے انہیں طبعی مناسبت ہو۔ کوئی افسانہ نگار اپنے کھوکھلے تنے سے سر باہر نکال کر تو دیکھے! کہانی تھمی ہوئی ہے۔ نقاد اور افسانہ نگار ایک مساواتِ جبریہ کے دونوں جانب کھڑے ہیں اور توجہ کا مرکز ان کے درمیان گہرا ہوتا ہوا دشمنی کا رنگ ہے۔ افسانے کی تخلیق اور تنقید کو میں دشمنی کے اسی تلازمے کی مختلف مثالوں کے درمیان تسلسل اور ارتباط خیالات کے طور پر دیکھ رہا ہوں کیونکہ افسانے سے متعلق کسی discourse میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایسے متحد الخیال استعاروں میں داستان نظر آنے لگے۔میرے شبہات تقویت حاصل کرلیتے ہیں جب محولہ بالا مضمون کے آغاز ہی میں رام لعل دشمنی کا ذکر چھیڑ کر وہی تلازمہ اختیار کرلیتے ہیں جو مجھے انتظار حسین اور ہنری جیمز کے ہاں نظر آیاتھا۔ دشمنی کے ڈر سے افسانہ نگار سہما ہوا ہے۔ دشمنی پرانی ہے، ڈر نیا ہے۔
آج یہ کیفیت ہے کہ جس رسالے میں (اپنی) تاز ہ کہانی چھپ کر آتی ہے تو اسے دیکھتے ہوئے ایک خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے میں اپنے قارئین کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اب میں ایسے لوگوں میں گھرا ہوا ہوں جو گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب میں کچھ لکھوں اور وہ میرا محاسبہ کریں۔ ان لوگوں میں میرے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔
دشمن! یہ نام سنتے ہی ہم چوکنا ہوجاتے ہیں۔ سانس تیز تیز چلنے لگتی ہے اور حواس کسی ممکنہ خطرے کی بوسونگھنے کے لیے چوکس۔ وہ اسی کھیت کی لمبی لمبی گھاس میں گھات لگائے بیٹھا ہوگا، وہ عیار ناقد، مکار قاری میرا ہم زاد کہ کسی پہلو سے کم زور دیکھ لے اور وار کرے۔ طلا یہ دینے والوں کی آنکھ ذرا جھپکی اور وہ دبے پائوں آئے، سرائچہ چاک کرکے خیمے میں آگھسے اور شب خون مار کر کام تما م کردے۔ تنقید کے ہاتھوں آج کے افسانہ نگار کی صورت حال، منیر نیازی کے الفاظ میں، ’’دشمنوں کے درمیان شام‘‘ بن کر رہ گئی ہے۔
تنقید کے خلاف فرد جرم بڑی سنگین ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس کی نیت میں فتور اور آستین پر لہو ہے۔ مگر خنجر سے رگِ گلو کارشتہ کچھ ایسا ہے کہ ہم دست و بازوئے قاتل کو دعائیں دیتے نظر آتے ہیں۔ تنقید کی خام کاریوں سے بیزار آکر بعض افسانہ نگاروں نے تنقید کے وجود یا اس کی اہمیت سے ہی انکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمر اور رتبے کے اعتبار سے ان میں ممتاز مفتی سرفہرست ہیں۔ نقادوں سے برہمی کے مرحلے سے گزر کر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ’’تنقید پر تو میں اعتماد ہی نہیں رکھتا‘‘۔کچھ اسی قسم کا بیان عبداللہ حسین نے بھی دیا ہے کہ جس میں تنقید کو غیرضرور سمجھا ہے۔ یہ نقطہ نظر بھی محض ایک آدھ فرد کا نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی صورت میں تنقید سے بریت کے اعلان کے طور پر گاہے بہ گاہے گونجتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ عام بیزاری، ہمارے نقادوں کی روش کا رد عمل ہو۔ خیر وجہ کچھ بھی ہو، یہ بھی انتہا پسند انہ رویہ ہے اور اتنا ہی غلط جتنا کہ نقادوں کے آگے سپر ڈال کر انہیں اپنا ماویٰ وملجا سمجھنا۔ تنقید کی افادیت کا احساس بھی افسانہ نگار کے ادبی apparatus کا حصہ ہے۔ جوزف اشکوورئیسکی کی جس گفتگو کا اوپر حوالہ دیا گیا، وہ شروع ہی اس طرح سے ہوتی ہے: ’’تنقید لازمی ہے، اس بات سے کوئی مفر نہیں۔ کئی وجوہات کی بنا پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے ممکنہ خطرات سے واقف رہنا چاہیے۔‘‘ ممکنہ خطرات کا یہ ادراک ازبس ضروری ہے کہ یہ درخت کے اندر چھپے سے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ گفتگو میں اشکووریئسکی آگے جاکر اس یقین کی بات کرنے لگتا ہے کہ جو لکھنے والے کو اپنی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہ میانہ روی کا قائل نہیں اور ہنری ملر پر چلنے والے فحاشی کے مقدمے کے دوران ایک صحافی کا کہا ہوا ہی جملہ، داد کے سے انداز میں دہراتا ہے۔
The artist must go too far so that others can go far enough.
گفتگو ’’سنہری اوسط‘‘ کی طرف مڑ گئی ہے کہ لیہم کا سوال ایک بار پھر اسے تنقید کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ سوال تنقید کے منصب کے بارے میں ہے مگر اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہ طور خاص توجہ طلب ہیں: ’’کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ تنقید ذہنی حفظان (Mental Hygiene) کو برقرار رکھنے کا کردار ادا کرتی ہے؟ اشکووریئسکی کا جواب اگر چہ اس فقرے کے پورے مضمرات کو نہیں سمیٹا پھر بھی دوٹوک ہے: ’’جب بھی تنقید کا سامنا کسی ایسی بے ایمانی سے ہو جو معاشرے کے کسی ایک حصے کے ذوق کو ورغلانے کی کوشش کررہی ہے تو تنقید کو تن دہی سے کام کرنا چاہیے۔ اسے ایمان دارانہ پیش کش اور اس کام میں تفریق کرنی چاہیے جو دلالی پر مشتمل ہے۔ اسے جعل سازی کو پہچان لینا چاہیے اور سطحی کام کو برملا برا کہنا چاہیے‘‘۔ اس کا مطلب میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ تنقید کی اصل دشمنی کھوکھلے تنے سے ہے، اس میں چھپے ہوئے پیغمبر سے نہیں۔ جو درخت پیغمبر کو چھپا نہیں سکے اسے تنقید کی کلہاڑی کی زد میں آناہی چاہئے۔ آخر دشمنی کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نقادوں نے سارا زور دوستی کے نباہنے پر دیا ہے۔ جیمز کا قریبی معاصر اور خود بہت پختہ تنقیدی شعور کا حامل ناول نگار، جوزف کو نریڈ، ادیب اور ناقد؍ قاری کے درمیان دوستی کاذکر کرتا ہے: ’’دوستی سے مراد دونوں کے درمیان بے تکلفی، خیالات اور احساسات کی بے تکلفی جیسے ایک آدمی کو دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بے غرض اور لازمی خلوص کہ آدمی کی عمیق ترین باطنی زندگی کسی اور وجود کی کھری ہم دردی پر دہرانے کی کوشش کررہی ہے۔‘‘ مگر ایسی دوستی بھلا کہاں قرین قیاس ہے اور اگر ممکن ہوتی بھی تو افسانہ نگار کی ایمائیت کو راس نہیں آتی جو شمع کی طرح جلتی ہے اور فنا پذیر ہے اور اسی طرح جل بجھنے میں اس کا سارا افسانہ مضمر ہے، افسانہ بھی او را س کے معنی بھی:
کرے ہے صرف بہ ایمائے شعلہ قصہ تمام
بطرز اہل فنا ہے فسانہ خوانی شمع
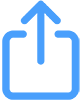 then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'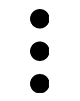 then 'Add to home screen'
then 'Add to home screen'







کوئی تبصرہ نہیں